 نومبر ۱۹۸۹ء میں دیوارِ برلن کے گرنے کے ساتھ ہی بین الاقوامی سیاست میں سرد جنگ بھی اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد مغربی سیاست دانوں، پالیسی سازوں اور دانشوروں نے آئندہ اپنی خارجہ پالیسی کے لیے ایک نئی حکمت عملی وضع کی۔ اس تعلق سے سب سے پہلے ایک امریکی مفکر فرانسس فوکویاما نے ۱۹۸۹ء میں ایک امریکی رسالے The National Interest میں The End of History (انتہائے تاریخ) کے نام سے ایک مضمون لکھا کہ مغربی تہذیب انتہائی عروج پر ہے اور یہ ساری دنیا پر چھا جائے گی۔ اسی مضمون میں فوکویاما نے Liberal Democracy کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہی انسان کی نظریاتی ترقی کی آخری فتح ہے اور یہ کہ دنیا میں رائج نظریات کے درمیان کشمکش ختم ہوگئی ہے اور مغربی آزاد جمہوریت کے سوا اب دنیا میں کوئی نیا نظریہ یا نظام آنے والا نہیں ہے۔ ۱
نومبر ۱۹۸۹ء میں دیوارِ برلن کے گرنے کے ساتھ ہی بین الاقوامی سیاست میں سرد جنگ بھی اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد مغربی سیاست دانوں، پالیسی سازوں اور دانشوروں نے آئندہ اپنی خارجہ پالیسی کے لیے ایک نئی حکمت عملی وضع کی۔ اس تعلق سے سب سے پہلے ایک امریکی مفکر فرانسس فوکویاما نے ۱۹۸۹ء میں ایک امریکی رسالے The National Interest میں The End of History (انتہائے تاریخ) کے نام سے ایک مضمون لکھا کہ مغربی تہذیب انتہائی عروج پر ہے اور یہ ساری دنیا پر چھا جائے گی۔ اسی مضمون میں فوکویاما نے Liberal Democracy کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہی انسان کی نظریاتی ترقی کی آخری فتح ہے اور یہ کہ دنیا میں رائج نظریات کے درمیان کشمکش ختم ہوگئی ہے اور مغربی آزاد جمہوریت کے سوا اب دنیا میں کوئی نیا نظریہ یا نظام آنے والا نہیں ہے۔ ۱
اس کے بعد برنارڈ لیوس نے اس نظریے کو نئے قالب میں پیش کرتے ہوئے Return of Islam کے نام سے مقالہ لکھا۔ پھر اس مقالے کو نئی شکل دے کرماہ نامہ Atlantic میں The Roots of Muslim Rage (مسلم غم و غصہ کی جڑ یں) کے زیرعنوان زہریلی تحریر بنا کر تہذیبی تصادم کا نظریہ پیش کیا:
دراصل ہم ایک ایسی تحریک اور صورت حال کا سامنا کر رہے ہیں جو حکومتوں، مسائل اور منصوبوں سے حد درجہ بڑھ کر ہے۔ یہ صورت حال ایک تہذیبی تصادم سے کم نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہودی عیسائی ورثے، ہمارے سیکولر اور ان دونوں کی ساری دنیا میں اشاعت کے قابل رد عمل ہے۔۲
پرسٹن یونی ورسٹی کے پروفیسر برنارڈ لیوس کا شمار اسلام اور مشرق وسطیٰ پر مغرب کے معروف دانش وروں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلے جذبات کا اظہار کرنے سے احتراز کرتے ہیں، لیکن اس ہاتھ کی صفائی کے باوجود متعصبانہ سوچ اور بغض چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تہذیبوں کے تصادم کی اصطلاح اور نظریے کے اصل خالق یہی ہیں ۔۳
برنارڈ لیوس کے بعد جس مغر بی مفکر اور پالیسی ساز نے تہذیبی تصادم کے نظریے کو انتہائی منظم انداز سے آگے بڑھایا، وہ ہارورڈ یونی ورسٹی کے پروفیسر سیموئیل پی ہن ٹنگٹن ہیں، جو نیشنل سیکورٹی کونسل میں منصوبہ بندی کے بھی ڈائرکٹر رہ چکے تھے۔ انھوں نے فرانسس فوکویاما کے نظریاتی کش مکش کے خاتمے کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے یہ پیش گوئی کی کہ: ’’آیندہ دنیا میں تصادم نظریات کی بنیاد پر نہیں بلکہ تہذیبوں کی بنیاد پر ہوگا۔  مغر بی تہذیب جو اس وقت غالب تہذیب کی صورت اختیار کر چکی ہے، پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے۔ اس کا اسلامی تہذیب سے ہر حال میں تصادم ہونا ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے‘‘۔ ہن ٹنگٹن نے ۱۹۹۳ء کے فارن افیئرز میں The Clash of Civilizations کے عنوان سے مضمون لکھا، جسے ۱۹۹۶ء میں پھیلا کر The Clash of Civilizations and Remaking of the New World Order (تہذیبوں کا تصادم اور نئے عالمی نظام کی تشکیل) کے نام سے کتابی شکل میں شائع کیا، اور پھر اس پر دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر مباحثے کا آغاز ہوا۔ نائن الیون کے بعد اس مباحثے نے نہ صرف طول پکڑا بلکہ شدت بھی اختیار کر لی۔
مغر بی تہذیب جو اس وقت غالب تہذیب کی صورت اختیار کر چکی ہے، پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے۔ اس کا اسلامی تہذیب سے ہر حال میں تصادم ہونا ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے‘‘۔ ہن ٹنگٹن نے ۱۹۹۳ء کے فارن افیئرز میں The Clash of Civilizations کے عنوان سے مضمون لکھا، جسے ۱۹۹۶ء میں پھیلا کر The Clash of Civilizations and Remaking of the New World Order (تہذیبوں کا تصادم اور نئے عالمی نظام کی تشکیل) کے نام سے کتابی شکل میں شائع کیا، اور پھر اس پر دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر مباحثے کا آغاز ہوا۔ نائن الیون کے بعد اس مباحثے نے نہ صرف طول پکڑا بلکہ شدت بھی اختیار کر لی۔
مغر بی مفکرین اور پالیسی سازوں نے اس مفروضے کو منطقی انداز میں پیش کر کے کہا کہ تہذیبوں (بالخصوص اسلامی اور مغربی تہذیب ) کے مابین تصادم اور ٹکراؤ لازم بلکہ ناگزیر بھی ہے۔ ہن ٹنگٹن کے مطابق آنے والے زمانے میں تصادم ، ٹکراؤ اور جنگ، سیاست، اقتصادیات اور سرحدوں پر ٹکراؤ کی بنیاد پر نہیں بلکہ تہذیبوں کی بنیاد پر ہوگی:
اس دنیا میں تصادم کا بنیادی سبب نہ تو مکمل طور پر نظریاتی ہوگا، اور نہ مکمل طور پر معاشی، بلکہ نوع انسان کو تقسیم کر نے والے بنیادی اسباب ثقافتی ہوں گے۔ عالمی معاملات میں قو می ریاستیں اہم کردار ادا کر تی رہیں گی، لیکن عالمی اہمیت کے بڑ ے تصادم ان ریاستوں اور گروہوں کے درمیان ہوں گے، جو مختلف تہذیبوں سے وابستگی کو اہمیت دیتے ہیں۔۴
مغر ب اپنی تہذیب کی عالم گیریت پر یقین رکھتا ہے اور اس کا تصور یہ ہے کہ مغرب کی تہذیبی بالاتری اگرچہ رُوبہ زوال ہے، لیکن ہن ٹنگٹن کے بقول: مغرب اپنی برتری (pre-eminent position) کو قائم رکھنے کے لیے کو شش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ وہ اپنے مفادات کو عالمی برادری کے مفادات کے طور پر پیش کرکے ان مفادات کی حفاظت کر رہا ہے۔۵
تہذیبوں کی تقسیم
 ماہرین نے تہذیبوں کا گہرائی سے مطالعہ پیش کیا ہے۔ مشہور مؤرخ ٹائن بی نے پہلے ۲۱ اور بعد میں دنیا کو ۲۳ تہذیبوں میں تقسیم کیا۔ اسپنگر نے دنیا کی آٹھ بڑی ثقافتوں کی نشان دہی کی، میک نیل نے تہذیبوں کی تعداد ۹بتائی، سلکیو نے ۱۲تہذ یبوں کی نشان د ہی کی ہے ۶، جبکہ خود ہن ٹنگٹن نے دنیا کی آٹھ بڑی تہذیبوں کا تذکرہ کیا اور کہا ہے کہ مستقبل میں تصادم انھی تہذیبوں کے درمیان ہوگا : ۱۔چینی ( کنفیوشس) ۲۔ جاپانی ۳۔ ہندو۴۔ اسلامی۵۔ قدامت پرست عیسائی ۶۔ لاطینی ۷۔ افر یقی۸۔ مغر بی تہذ یب۔
ماہرین نے تہذیبوں کا گہرائی سے مطالعہ پیش کیا ہے۔ مشہور مؤرخ ٹائن بی نے پہلے ۲۱ اور بعد میں دنیا کو ۲۳ تہذیبوں میں تقسیم کیا۔ اسپنگر نے دنیا کی آٹھ بڑی ثقافتوں کی نشان دہی کی، میک نیل نے تہذیبوں کی تعداد ۹بتائی، سلکیو نے ۱۲تہذ یبوں کی نشان د ہی کی ہے ۶، جبکہ خود ہن ٹنگٹن نے دنیا کی آٹھ بڑی تہذیبوں کا تذکرہ کیا اور کہا ہے کہ مستقبل میں تصادم انھی تہذیبوں کے درمیان ہوگا : ۱۔چینی ( کنفیوشس) ۲۔ جاپانی ۳۔ ہندو۴۔ اسلامی۵۔ قدامت پرست عیسائی ۶۔ لاطینی ۷۔ افر یقی۸۔ مغر بی تہذ یب۔
جنگجو سیاسی مفکر، ہن ٹنگٹن نے تہذیبی تصادم کے اس دور میں تین تہذیبوں کو اہم قرار دیا ہے: ۱۔ مغر بی تہذیب ۲۔چینی تہذیب ۳۔ اسلامی تہذیب۔ ہن ٹنگٹن کے مطابق پانچ تہذیبوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یا مغرب کے ساتھ جزوی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف تصادم کی صورت اختیار نہیں کرے گا۔
تہذیبی تصاد م کے عوامل
ہن ٹنگٹن کے مطا بق اسلام اور مغرب کے درمیان اختلاف اور باہمی تنازعے کو روز بہ روز بڑھاوا مل رہا ہے، جن میں پانچ عوامل کو مرکزیت حاصل ہے:
(۱) مسلم آبادی میں اضافے نے بےروزگاری اور بد دل اور مایوس نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو جنم دیا ہے جو اسلامی تحریکوں میں داخل ہو جاتے اور مغرب کی طر ف نقل مکانی کر تے ہیں۔
(۲) اسلامی نشاتِ ثانیہ نے مسلمانوں کو اپنی تہذیب کی امتیازی خصوصیات اور مغر بی اقدار کے خلاف نیا اعتماد عطا کیا ہے۔
(۳) مغر ب کا اپنی قدروں اور اپنے اداروں کو عالم گیر بنانے اور اپنی خوبی اور اقتصادی برتری قائم کرنے اور عالم اسلام میں موجود اختلافات میں مداخلت کی مسلسل کوشش مسلمانوں میں شدید ناراضی پیدا کر تی ہے ۔
(۴) اشتراکیت کے انہدام نے مغر ب اور اسلام کے ایک مشترکہ دشمن کو منظر سے ہٹایا، مگر ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ایک بڑے متوقع خطرے کی صورت میں لاکھڑا کیا ہے۔
(۵) اسلام اور مغرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات ان کے اندر یہ احساس ابھارتے ہیں کہ ان کی شنا خت کیا ہے اور وہ ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں۔۷
ہن ٹنگٹن کے مطابق تہذیبوں کا تصادم انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر واقع ہوتا ہے۔ انفرادی سطح پر تصادم، تہذبیوں کے درمیان فوجی ٹکراؤ اور ایک دوسرے کے علاقے پر قبضہ جمانے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اجتماعی سطح پر مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والی حکو متیں علاقوں میں اپنی فوجی و سیاسی برتری کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ اپنی اپنی سیاسی اور مذہبی اقدار کے فروغ کے لیے ایک دوسرے پر برتری لینے کی تگ و دو میں رہتے ہیں۔ ۸
اسلام اور مغرب کے درمیان کش مکش
ہن ٹنگٹن کے نزدیک، اسلام اور مغربی تہذ یب کے درمیان تصادم پچھلے۱۳۰۰ سال سے جاری ہے۔ اسلام کے آغاز کے بعد عربوں نے مغرب پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد صلیبیوں نے عیسائی حکومت قائم کرنے کی کوششیں کیں۔ انیسویں اور بیسویں صدی کے ابتدائی دور میں عثمانی حکومت بھی زوال پذیر ہوگئی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی حکومتیں قائم ہوگئیں اور شمالی افریقہ کے علاوہ، مشر ق وسطیٰ پر مغرب کا اقتدار قائم ہوا۔۹
 اسلام اور عیسائیت، مسیحی اور مغربی دونوں کے درمیان تعلقات اکثر ہنگامہ خیز رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہے ہیں۔ آزاد جمہوریت اور مارکسی لنین ازم کے درمیان انیسویں صدی کا تنازع اسلام اور عیسائیت کے درمیان مسلسل اور گہرے مخاصمانہ تعلقات کے مقابلے میں ایک عارضی اور سطحی مظہر ہے۔۱۰ ہن ٹنگٹن کو معلوم تھا کہ مغرب، اسلام کے خلاف سیاسی پروپیگنڈے اور سیاسی سازشوں سے زیادہ دیر تک عالم اسلام میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا اور نہ فوجی اور اقتصادی بنیادوں پر باقی دنیا کو اپنے پنجۂ استبداد میں رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اسلام اور اس کی تہذیب کو مغرب کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا:
اسلام اور عیسائیت، مسیحی اور مغربی دونوں کے درمیان تعلقات اکثر ہنگامہ خیز رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہے ہیں۔ آزاد جمہوریت اور مارکسی لنین ازم کے درمیان انیسویں صدی کا تنازع اسلام اور عیسائیت کے درمیان مسلسل اور گہرے مخاصمانہ تعلقات کے مقابلے میں ایک عارضی اور سطحی مظہر ہے۔۱۰ ہن ٹنگٹن کو معلوم تھا کہ مغرب، اسلام کے خلاف سیاسی پروپیگنڈے اور سیاسی سازشوں سے زیادہ دیر تک عالم اسلام میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا اور نہ فوجی اور اقتصادی بنیادوں پر باقی دنیا کو اپنے پنجۂ استبداد میں رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اسلام اور اس کی تہذیب کو مغرب کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا:
مغرب کا بنیادی مسئلہ اسلامی بنیاد پر ستی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام ہے جو ایک مختلف تہذیب ہے جس کے ماننے والے لوگ اپنی ثقافت کی برتری کے قائل اور اپنی طاقت کی کمتری پر پریشان ہیں۔ ۱۱
ہن ٹنگٹن مذہبی عالم گیریت، بالخصوص اسلامی عالم گیریت کا اطلاقی اندازہ لگاتا ہے۔ مراد ہوف مین کے بقول: ہن ٹنگٹن غلط ہو سکتا ہے، لیکن وہ احمق ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی بنیاد پرستی، دہشت گردی، انتہا پسندی اور سیاسی اسلام جیسے الزامات لگانے میں مغر ب کا بنیادی ہدف اسلام ہے۔ اور اس نے اس کے لیے بےشمار ذرائع کو استعمال میں لا کر راے عامہ کو ہموار کیا، تاکہ پوری دنیا اسلام اور عالم اسلام کے خلاف صف آرا ہو جائے۔ مغر ب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ مغربی فکر اور تہذیب کا اگر کسی تہذ یب میں مقابلہ کر نے کی صلاحیت اور طاقت ہے تو وہ صرف اسلامی تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب میں متبادل پیش کر نے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، جو ان کے مطابق اگرچہ فی الوقت ایسا نہیں ہو رہا ہے لیکن مستقبل میں ایسا ضرور ہوگا۔ اسی لیے ان کے صحافی، مصنفین، ادبا، مفکرین ، پالیسی ساز، اداکار اور سیاست داں اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ The Red menace is gone, but here is Islam ۱۲ (سرخ خطرے کا خاتمہ ہوگیا، لیکن اب اسلام ہے)۔
اسی لیے مغربی ماہرین ، اسلامی تحر یکات اور احیاے اسلام کو مغرب کے لیے خطر ے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اسلام کو اپنا اصل دشمن قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں انھوں نے اسلام کو شکست دینا اپنا ہدف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک مغر بی انتہاپسند ڈینیل پایپس [امریکی تھنک ٹینک Middle East Forum کے صدر] نے یروشلم پوسٹ میں The Enemy has a Name کے عنوان سے مضمون میں لکھا ہے:’’ اصل میں یہ دشمن ایک واضح اور جامع نام رکھتاہے اور وہ ہے’اسلام ازم‘۔ اسلام کے تخیلاتی پہلو کا انقلابی تصور، اسلام پرست آمرانہ نظریہ کہ جو بھرپور مالی مدد سے اسلامی قوانین ( شریعہ) کو عالمی اسلامی ضابطے کے طور پر نافذ کر نے کا خواب ہے ‘‘۔۱۳ وہ ایک انٹرویو میں اس بات کا بھی برملا اظہار کرتا ہے:
میں کئی عشروں سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ ’ریڈیکل اسلام‘ مسئلہ بنا ہوا ہے اور ’جدید اسلام‘ ہی اس مسئلے کا حل ہے۔۱۴
ا س حوالے سے ایڈورڈ سعید کامشاہدہ اس طر ح ہے:
یورپ اور امریکا کے عام لوگوں کے لیے آج اسلام انتہائی ناگوار خبر کا عنوان بنا ہوا ہے۔ وہاں کا میڈیا، حکو مت، پالیسی ساز اور محققین یہ تسلیم کیے بیٹھے ہیں کہ اسلام، مغربی تہذ یب کے لیے خطرہ ہے۔۱۵
یہ سلسلہ بیسویں صدی کے آٹھویں عشرے سے مسلسل آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پہلے اسلام کو خطر ے کے طور پر پیش کرنا اور اس کے بعد تہذیبی تصادم کے نظریے کو وجود میں لانا مغرب کی اہم کارستانیاں ہیں۔۱۶ امریکی پالیسی ساز ادارے رینڈ کارپوریشن نے ۲۰۰۴ء میں مسلمانانِ عالم پر ایک مفصل رپورٹ تیار کی، جس کا عنوان Civil Democratic Islam: partners resources and strategies ہے۔ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکا اور مسلمان ایک دوسرے کے حریف ہیں، جس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کا دینی رجحان ہے۔۱۷مسلمانوں کی بڑ ھتی ہوئی آبادی سے ہن ٹنگٹن اور دیگرمغر بی مفکر ین کو زبردست تشویش لاحق ہے۔ ہن ٹنگٹن کے بقول: مسلمانوں کی بڑ ھتی ہوئی آبادی مغر ی اور یورپی ممالک کے لیے خطر ہ بنتی جا رہی ہے۔ دنیا کے دو بڑے تبلیغی مذاہب اسلام اور عیسائیت کے ساتھ وابستگی رکھنے والوں کے تناسب میں گذشتہ ۸۰ برسوں میں بےحد اضافہ ہو۔۱۹۰۰ء میں دنیا کی کل آبادی میں مغربی عیسائیوں کی تعداد کا اندازہ ۹ء۲۶ فی صد اور ۱۹۸۰ء میں ۳۰ فی صد لگا یا گیا۔ اس کے برعکس ۱۹۰۰ء میں مسلمانوں کی کل آبادی ۴ء۱۲فی صد اور ۱۹۸۰ء میں ۵ء۱۶ یا دوسرے اندازے کے مطابق ۱۸فی صد تک بڑھ گئی۔ ہن ٹنگٹن نے مغرب میں مسلمانوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی سے خبردار کرتے ہوئے لکھا ہے:
عیسائیت تبدیلیِ مذہب سے پھیلتی ہے، جبکہ اسلام تبدیلی مذہب اور افزایش نسل سے پھیلتا ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب ڈرامائی طور پر بڑھ کر بیسویں صدی کی تبدیلی کے وقت دنیا کی کل آبادی کا ۲۰ فی صد ہو گیا اور چند برسوں بعد ۲۰۲۵ء میں یہ تعداد دنیا کی کل آبادی کی تقریباً ۳۰ فی صد ہوگی‘‘۔۱۸
مغربی دانش وروں نے اسلام اور مغربی تہذیب کے درمیان تصادم، مختلف پہلوؤں سے ظاہر کرنے کے لیے بے شمار حر بے استعمال کیے۔ اسلام پر پہلے شبہات کو جنم دیا، اور پھر الزامات عائد کرکے تصادم کے لیے راہیں ہموار کی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ: اسلام، جدیدیت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مغربی فکر و تہذیب، ثقافت اور عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے۔ پھر اسلام اور جمہوریت میں کوئی مطابقت نہیں بلکہ واضح تضاد ہے۔
- تہذیب کی حقیقت:
’تہذ یب‘ عر بی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی تربیت، اصلاح، دوستی اور شائستگی کے ہیں۔ فیروزاللغات میں اس کے یہ معنی بیان کیے گئے ہیں: شائستگی، آراستگی، صفائی، اصلاح اور خو ش اخلاقی ۔۱۹
مشہور انگریزی لغت یونیورسل انگلش ڈکشنری میں یہ معنی دیے گئے:
Civilization : A state of social, moral, intellectual and industrial development.۲۰
یعنی انسان کے سماجی، اخلاقی، فکر ی اور اس کی ترقیاتی تعمیر کے مختلف پہلوؤں کا نام تہذیب ہے۔
’تہذیب‘ ایک ایسی اصطلاح ہے، جس میں کافی وسعت پائی جاتی ہے۔ اس میں تصورِ زندگی، طرزِ زندگی، زبان ، علم وادب، فنونِ لطیفہ، رسوم و رواج، اخلاق و عادات، رہن سہن، کھانے پینے کا انداز، خاندانی و قومی روایات، فلسفہ و حکمت، لین دین، اور سماجی معاملات، سب شامل ہیں۔ یہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سنوارنے کا بھی نام ہے۔
اسلام نے تہذیب کو نہ صرف مزید وسعت اور جامعیت بخشی بلکہ اسے اخلاق عالیہ کے مرتبے تک پہنچایا۔ اسلام نے تہذیب کو دین و دنیا سنوارنے اور اصلاح کرنے کا ذریعہ بھی بتایا، کیوں کہ اس میں انسان کے اخلاق و کردار، معاملات و معاشرت، تعلیم و تمدن، سیاست، معیشت، قانون اور اداروں کی اصلاح، ان کو درست رکھنے کے لیے اصل رہنمائی موجود ہے۔ اسلام مکمل دین ہے۔ اس نے جہاں انسان کو کارِ جہاں چلانے کے لیے مکمل رہنمائی دی، وہیں اسے ایک مکمل تہذیب بھی عطا کی۔
اسلام: تہذیبی تصادم یا مکالمہ اور مفاہمت
کیا تہذیبوں کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے؟ یا کیا تہذیبیں تصادم کی طر ف جا رہی ہیں ؟ اس حوالے سے اسلام کا موقف بہت واضح ہے۔
اسلام تہذیبوں کے تصادم کا قائل نہیں۔ اسلام نے تو ماضی میں بھی دوسری تہذیبوں سے تصادم اور جنگ کے بجاے دعوت کے راستے ہی کو اوّلیت دی ہے۔ بقول پروفیسر خورشید احمد: ’’تہذیبوں میں مکالمہ، تعاون، مسابقت حتیٰ کہ مثبت مقابلہ سب درست لیکن تہذیبوں میں تصادم، جنگ و جدال، خون خرابا اور ایک دوسرے کو مغلوب اور محکوم بنانے کے لیے قوت کا استعمال انسانیت کے شر ف اور تر قی کا راستہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تہذیبوں کا تصادم ہمارا لائحہ عمل نہیں۔ یہ مسلمانوں پر زبردستی ٹھونسا جارہا ہے‘‘۔ ۲۱ مراد ہوف مین کے نزدیک: ’’ تہذیبوں کے ارتقا میں کبھی کوئی زیرو پوائنٹ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر شخص نے کسی دوسرے شخص سے فیض پایا اور ہر شخص نے کسی دوسرے شخص کی کامیابیوں پر اپنی عمارت کھڑی کی ہے‘‘۔۲۲
اسلامی تہذیب نے اپنا دامن بہت وسیع رکھا ہے، تنگنائیوں اور محدودیت کے دائرے کی کوئی گنجایش نہیں رکھی۔ اسی لیے اس نے ہر دور میں اور ہر جگہ ہردل عزیز رہنما اور تاب ناک نقوش چھوڑے ہیں اور ہر تہذیب کو فائدہ پہنچایا ہے۔ مغر بی دانش ور اس بات کا خو د بھی اعتراف کر تے ہیں۔ برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلس نے ستمبر ۱۹۹۲ء میں اوکسفرڈ یونی ورسٹی کے اسلامی سنٹر میں تقریر کر تے ہو ئے کہا کہ: ’’ہماری تہذیب و تمدن پر اسلام کے جو احسانات ہیں، ہم ان سے بڑی حد تک ناواقف ہیں۔ وسطی ایشیا سے بحراوقیانوس کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی اسلامی دنیا علم و دانش کا گہوارہ تھی، لیکن اسلام کو ایک دشمن مذہب اور اجنبی تہذیب قرار دینے کی وجہ سے ہمارے اندر اپنی تاریخ پر اس کے اثرات کو نظرانداز کرنے یا مٹانے کا رجحان رہا ۔ مغرب میں احیا ے تہذیب کی تحریک میں مسلم اسپین نے گہر ے اثرات ڈالے۔ یہاں علوم کی ترقی سے یورپ نے صدیوں بعد تک فائدہ اٹھایا‘‘ ۔ ۲۴
اسلام نے کبھی عیسائیت کے خلاف جارحانہ محاذ آرائی نہیں کی اور نہ عیسائیوں کو اپنا دشمن باور کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں نے عیسائیوں کو دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے نہ صرف اُبھارا بلکہ تاکید بھی کی۔ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ محض اللہ کے وجود کے قائل ہیں بلکہ وہ بہت سے انبیاے کرام ؑ پر ایمان رکھتے ہیں، جن میں حضرت ابراہیم ؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوب ؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت موسٰی ؑشامل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی انبیاے کرام ؑ ہیں، جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن مجید اور بائبل میں ہے۔ جب دور نبوت میں مسلمان ابتلا و آزمایش کا شکار ہوئے تو انھوں نے حبشہ کے ایک عیسائی بادشاہ کے ہاں ہجرت کی۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ عیسائیت ہی کیا، اسلام نے کبھی بھی مذہب، تہذیب، نسل یا کسی بھی علاقے کے رہنے والوں کو اپنا دشمن تصور نہیں کیا لیکن فساد پھیلانے والوں کی مذمت اور مزاحمت ضرور کی۔
مکالمے کی اہمیت
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو راہ حق کی طر ف دعوت دینے اور ان کے خدشات کو دور کر نے کے لیے متعدد ذرائع اختیار کر نے کی تعلیم دی ہے۔ جن میں سے ایک ذریعہ مکالمہ (Dialogue) بھی ہے۔ یہ دعوت کا ایک انتہائی مؤثر، پُرکشش اور آسان ذریعہ ہے۔ قرآن کر یم میں متعدد مکالموں کا تذکرہ آیا ہے، مثلاً: (۱) حضرت ہودؑ کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ، (۲) حضرت موسٰیؑ کا اپنی قوم سے مکالمہ، (۳) حضرت ابراہیم ؑ کا اپنے باپ آزر اور نمرود کے ساتھ مکالمہ، (۴) حضرت یوسف ؑ کا زنداں کے ساتھیوں کے ساتھ مکالمہ، (۵) ملحد اور موحد شخص کے درمیان مکالمہ ،وغیرہ وغیرہ۔
اسلام میں دوسرے مذاہب اور تہذیبوں سے مکالمہ کرنے پر ابھارا گیا ہے، تاکہ اللہ کی زمین پر عدل و انصاف، حقوق انسانی کا لحاظ اور فساد، جنگ و جدل، قتل وغارت گری کا خاتمہ ہو، اور اقدار پر مبنی ایک پرامن اور صحت مند سماج وجود میں آئے۔ اسلام کا مزاج عملاً دعوتی ہے۔ اس لیے مکالمہ اس کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کے سخت ترین دشمن سے بھی مکالمے کے ذریعے تعلق پیدا کرنا فرائض دعوت میں شامل ہے۔ شرک اور طاغوت سے نفر ت تو کی جائے گی، لیکن مشرک اور طاغی کو مسلسل مکالمے کے ذریعے حق کی دعوت دی جاتی رہے گی، نفرت شرک سے ہے، مشرک سے نہیں۔ مکالمے میں مخاصمت، نزاع اور جرح کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باہم محبت و اُلفت اور عزت و اکرام کا خاص خیال رکھا جائے، نیز الزامات اور طعن و تشیع سے بالکل گریز کیا جائے۔ اس کے علاوہ خوشگوار انداز، تعلقات اور ماحول میں مکالمہ کیا جائے اور خوش اسلوبی کوا ختیار کیا جائے۔
مکالمے کے تین بنیادی اصول
(۱) مشترکہ باتوں کو موضوعِ گفتگو بنانا (۲) تعارف اور (۳) دعوت و تبلیغ کے اصول
۱۔ قرآن کریم نے اہل کتاب کے ساتھ مشترکہ باتوں کو موضوعِ گفتگو بنانے کے لیے ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
[pullquote]قُلْ یٰٓاَھْلَ الْکِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَۃٍ سَوَآءٍ م بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰہَ وَ لَا نُشْرِکَ بِہٖ شَیْءًا وَّ لَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْھَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ o( اٰل عمرٰن۳:۶۴) [/pullquote]
’’اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمھارے درمیان یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں۔ اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے‘‘۔ اس دعوت کو قبول کر نے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم (صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے) ہیں۔
اسی آیت میں یہود و نصاریٰ کو ان کے ظلم و جبر اور ان کے مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر اے کافرو یا اے مشر کو! کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ انھیں ایسے لقب سے خطاب کیا گیا ہے جس میں ان کے بھرپور عزت و اکرام کا لحاظ رکھا گیا۔
اسلام اور عیسائیت یا مغرب کے درمیان مکالمے کا آغاز دور نبوت سے ہی ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ؐ نے مشر ق و مغرب کے حکمرانوں کو کھلے دل سے نیک تمناؤں اور خیرخواہی کے ساتھ اسلام کے عالم گیر پیغام پر غور اور تسلیم کرنے اور انھیں کفر و ظلمات سے نکل کر نور اسلام کو اختیار کرنے پر دعوت دی تھی۔ قبولِ دعوت کی صورت میں انھیں دین و دنیا کی کامیابی اور سلامتی کی خوش خبر ی بھی سنائی گئی۔ اہل کتاب کے فرماں رواؤں کے نام اللہ کے رسول ؐ نے جو دعوتی خطوط بھیجے ہیں، ان میں اسلام قبول کر نے کی دعوت دینے کے بعد یہ جملہ بھی ہے: [pullquote]یُؤْتِکَ اللّٰہُ اَجْرَکَ مَرَّتَیْنِ۲۴[/pullquote]
اللہ تمھیں دہرے اجر سے نوازے گا۔
مغرب سے مذاکرات اور مکالمہ کی جتنی پہلے ضرورت تھی آج موجودہ دور میں اس سے کئی درجے زیادہ ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ۲۰۰۷ء میں عالم اسلام کے ۱۳۸؍اسلامی دانش وروں نے عیسائی رہنماؤں کے نام A common word between us and you کے عنوان سے ایک کھلا خط لکھا، جس میں بہت سی مشترکہ باتوں کا تذکرہ کیا گیا ۔ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طر ح کی پیش رفت کو آگے بڑھایا جائے ۔۲۵
مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان باہم تعارف ہو، تاکہ ایک دوسرے کے موقف کو سمجھ کر معاملات طے کر نے میں آسانی ہو۔ تعارف سے ہی نزاع، ٹکراؤ، تصادم اور جنگ کے مختلف اسباب کو اچھی طر ح سے ختم کیا جاسکتا ہے ۔ایک دوسرے کو جاننے اور تعارف حاصل کر نے کے بےشمار فوائد ہیں، جیسے آپس میں محبت سے رہنا، ایک دوسرے کے قریب آنا، ایک دوسرے سے اخذ و استفادہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :ٰٓ
[pullquote]یاََیُّھَا النَّاسُ اِِنَّا خَلَقْنٰکُمْ مِّنْ ذَکَرٍ وَّاُنثٰی وَجَعَلْنٰکُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآءِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰکُمْ ط اِِنَّ اللّٰہَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ o (الحجرات ۴۹:۱۳)[/pullquote]
لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمھاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمھارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناًاللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔
اس آیت مبارکہ میں تمام تہذیبوں کی تعمیر و بقا اور باہم تال میل اور ساتھ رہنے کے رہنما اصول موجود ہیں۔ پہلے تمام انسانوں سے بلالحاظ مذہب و ملت خطاب کیا گیا:’’ اس لحاظ سے تمام انسان اپنے اختلافات، تنوع اور زمان ومکاں کی دوری کے باوجود ایک انسانی اصل سے باہم مربوط ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس حقیقت کو اچھی طر ح اپنے دل و دماغ میں جاگزیں کرلیں اور اس کو ایک اخلاقی ضابطے کی حیثیت سے اپنے لیے اختیار کر لیں۔ اور اسی نقطۂ نظر سے دیگر قوموں اور تہذیبوں کو بھی دیکھیں ۔گویا کہ وہ روے زمین پر بسنے والے ایک ہی خاندان کے افراد ہیں‘‘۔ ۲۶
لِتَعَارَفُوْا کے بارے میں علا مہ ابن کثیر لکھتے ہیں: ای لیحصل التعارف بینھم کل یر جع الی قبیلتہ ۲۷ یعنی قبیلے کا ہر آدمی باہم تعارف حاصل کر ے۔
دعوت و تبلیغ کے اصول
اسلام کے پیغام رحمت و عدل کو عام کر نا اور اس کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں تک پہنچانا مسلمانوں کا بنیادی اور سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس فریضے سے غفلت اور کوتاہی برتنا ایک مسلمان کے ہرگز شایان شان نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے چند اہم باتوں کو ذہن میں تازہ رکھنا بےحد ضروری ہے۔ اس میں حکمت، خیرخواہی اورقولِ سدید خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ نیز مدعو قوم سے گفتگو انتہائی عمدہ طر یقے سے کر نے کی تاکید بھی کی گئی ہے:
[pullquote]اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ وَ الْمَوْعِظَۃِ الْحَسَنَۃِ وَ جَادِلْھُمْ بِالَّتِیْ ھِیَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّکَ ھُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیْلِہٖ وَ ھُوَ اَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِیْنَ o (النحل ۱۶:۱۲۵)[/pullquote]
اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمھارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اورکون راہِ راست پر ہے۔
اس آیت میں تین بنیادی اصولوں کا تذکرہ کیا گیا کہ حق سے آشنا لوگوں تک کیسے پیغام الٰہی پہنچایا جائے، اور ان کو کس طر ح سے پیغام حق کی طرف دعوت دی جائے۔ دعوت و تبلیغ کے یہ تینوں اصول وہی ہیں جو منطقی استدلال میں عموماً کام میں لائے جاتے ہیں۔ ایک تو برہانیات جن میں یقینی مقدمات کے ذریعے سے دعوے کے ثبوت پر دلیلیں لائی جاتی ہیں، دوسرے خطبات جن میں مؤثر اقوال سے مقصود کو ثابت کیا جاتا ہے، اور تیسرا اصول فریقین کے مسلّمہ مقدمات سے استدلال کیا جانا ہے۔ ۲۸ لہٰذا، دعوت و تبلیغ کے یہ تین اصول، یعنی حکمت و موعظت حسنہ اور جدال احسن جواہر پاروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔
مراجع ومصادر
۱۔ فوکویاما، The End of History، ۱۹۹۲ء ۲۔ برنارڈ لیوس، ماہ نامہ The Atlantic، ستمبر ۱۹۹۰ء
۳۔ لیوس کی چند کتب What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response ،۲۰۰۲ء، Crisis of Islam، ۲۰۰۳ء، مقالہ Muslims to the War on Europe، یروشلم پوسٹ، ۲۹ جنوری ۲۰۰۷ء۔ ۴۔ ہن ٹنگٹن ، مجلہ فارن افیئرز، گرما، ۱۹۹۰ء۔
۵۔ ہن ٹنگٹن، تہذیبوں کا تصادم، ترجمہ: محمد شفیع شریعتی، سری نگر، ۲۰۱۳ء، ص ۲۵۴۔
۶۔ حوالہ سابق، ص ۶۱ ۷۔ حوالہ سابق، ص ۲۳۹ ۸۔ہن ٹنگٹن ،مجلہ فارن افیئرز، گرما، ۱۹۹۰ء۔
۹۔ ایضاً ۱۰۔ ہن ٹنگٹن، تہذیبوں کا تصادم،ص ۲۹۰
۱۱۔ مراد ہوف مین، تہذیبوں کا تصادم، اکیسویں صدی میں،سہ ماہی مغرب اور اسلام، اسلام آباد، جولائی تا دسمبر۲۰۰۰ء۔
۱۲۔ عبداللہ احسن، The Clash of Civilizations Thesis and Muslims، مشمولہ Islamic Studies، گرما، ۲۰۰۹ء،ص ۱۹۸۔
۱۳۔ ڈینیل پایپس، The Enemy Has a Name، یروشلم پوسٹ، ۱۹ جون ۲۰۰۹ء۔
۱۴۔ ڈینیل پایپس، Radical Islam Creates Terrorism، دی ٹائمز آف انڈیا، ۲۱مارچ ۲۰۱۶ء
۱۵۔ ایڈورڈ سعید: Covering Islam، نیویارک ۱۹۸۱ء، ص ۱۳۶۔
۱۶۔ تفصیل دیکھیے: جان اسپوزٹیو، The Islamic Threat, Myth or Realty، نیویارک ۱۹۹۹ء۔
۱۷۔ احمد سجاد، مغرب سے نفرت کیوں؟ سہ ماہی مطالعات، جلد۶، شمارہ ۱۷، ۱۸،۱۹۔
۱۸۔ پروفیسر ہن ٹنگٹن ، تہذیبوں کا تصادم، ص ۹۰۔
۱۹۔ فیروز اللغات، دارالکتاب، دیوبند، یوپی، ۱۹۹۹ء، ص ۳۹۵۔
۲۰۔ The Universal English Dictionary
۲۱۔ پرو فیسر خورشید احمد، تہذیبوں کا تصادم۔ حقیقت یا واہمہ ،تر جمان القرآن لاہور مئی ۲۰۰۶ء،ص۲۲
۲۲۔ مرادہوف مین، تہذیبوں کا تصادم اکیسویں صدی میں،سہ ماہی مغرب اور اسلام،اسلام آباد، جولائی تا دسمبر ۲۰۰۰ء
۲۳۔ مولانا عیسیٰ منصوری، مغرب اور عالم اسلام کی فکری و تہذیبی کش مکش ،ورلڈ اسلامک فورم، ۲۰۰۰ء،ص:۸۸
۲۴۔ ڈاکٹر انیس احمد ،تہذیبی روایات کا مکالمہ، سہ ماہی مغرب اور اسلام، اسلام آباد، جنوری تا مارچ،۲۰۰۱ء۔
۲۵۔ تفصیل کے لیے دیکھیے،islamic studies ,A common word between us and you, 2008,p:243 to 263.
۲۶۔ زکی المیلاد ،تہذیبوں کے باہمی تعلقات: مفاہمت ومذاکرات،(اردوترجمہ،ڈاکٹر نگہت حسین ندوی)، انسٹی ٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹیڈیز، ۲۰۰۴،ص۳۱
۲۷۔ عمادالدین ابی الفداء اسماعیل بن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، دارالاشاعت دیو بند، ۲۰۰۲ء، ص۲۷۵
۲۸۔ علامہ سید سلیمان ندوی، سیرۃالنبی، دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ،۲۰۰۳، جلد:۴، ص۲۵۷
 ثقافت کیا ہے؟ ثقافت کسی خطۂ ِ زمین اور کسی شہر اور بستی کے رہنے والے لوگوں کے عادات و اطوار ، مدتوں کے تجربات سے ماخوذ تصورات ، انہی تجربات ہی سے مقبول و مروج ہونے والی سماجی روایات ، وہاں کے رسوم و رواج سب ثقافت کی تعریف میں آتے ہیں۔ اس ثقافت کا رنگ بعض اوقات مذہب پر بھی غالب آ جاتا ہے اور تمام ثقافتی رسوم و روایات کوe baptizکر کے اور ’کلمہ پڑھا ‘ کرمذہبی تقدس فراہم کر دیا جاتا ہے۔ہمارے شہرہوں یا دیہات، ہر جگہ شادی بیاہ اور موت مرگ کی بہت سی ایسی رسمیں رائج ہیں جو خواہ کیسی ہی اوٹ پٹانگ اور بے معنی ہوں اور ان کا مذہب سے دور پار کا بھی کوئی تعلق نہ ہو لیکن ان کو ادا کرتے وقت ’درود‘ (دعا) کا اہتمام کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ گائوں اور محلے کے مولوی صاحب کو ان کے ادا کرنے کا کچھ نہ کچھ نقد یا اجناس کی صورت میںصلہ ضرور ملتا ہے اس لیے وہ نہ صرف یہ کہ ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتے بلکہ ان رسموں کو ’کلمہ پڑھانے ‘ اور بڑے سوز اور خضوع و خشوع کے ساتھ ’درود ‘ پڑھنے میں جاہل لوگوں سے بڑھ کر کردار ادا کرتے ہیں۔مہندی اور مائیوں اور اس طرح کی دسیوں تقریبات میں واہیات، حیا سوز اور اخلاق باختہ حرکات اور خلافِ شریعت رسوم سے پہلے مولوی صاحب سے ’درود‘ دلوایا جاتا ہے۔
ثقافت کیا ہے؟ ثقافت کسی خطۂ ِ زمین اور کسی شہر اور بستی کے رہنے والے لوگوں کے عادات و اطوار ، مدتوں کے تجربات سے ماخوذ تصورات ، انہی تجربات ہی سے مقبول و مروج ہونے والی سماجی روایات ، وہاں کے رسوم و رواج سب ثقافت کی تعریف میں آتے ہیں۔ اس ثقافت کا رنگ بعض اوقات مذہب پر بھی غالب آ جاتا ہے اور تمام ثقافتی رسوم و روایات کوe baptizکر کے اور ’کلمہ پڑھا ‘ کرمذہبی تقدس فراہم کر دیا جاتا ہے۔ہمارے شہرہوں یا دیہات، ہر جگہ شادی بیاہ اور موت مرگ کی بہت سی ایسی رسمیں رائج ہیں جو خواہ کیسی ہی اوٹ پٹانگ اور بے معنی ہوں اور ان کا مذہب سے دور پار کا بھی کوئی تعلق نہ ہو لیکن ان کو ادا کرتے وقت ’درود‘ (دعا) کا اہتمام کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ گائوں اور محلے کے مولوی صاحب کو ان کے ادا کرنے کا کچھ نہ کچھ نقد یا اجناس کی صورت میںصلہ ضرور ملتا ہے اس لیے وہ نہ صرف یہ کہ ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتے بلکہ ان رسموں کو ’کلمہ پڑھانے ‘ اور بڑے سوز اور خضوع و خشوع کے ساتھ ’درود ‘ پڑھنے میں جاہل لوگوں سے بڑھ کر کردار ادا کرتے ہیں۔مہندی اور مائیوں اور اس طرح کی دسیوں تقریبات میں واہیات، حیا سوز اور اخلاق باختہ حرکات اور خلافِ شریعت رسوم سے پہلے مولوی صاحب سے ’درود‘ دلوایا جاتا ہے۔

 بیکن ہاؤس سکول سسٹم نے پنجابی میں گفتگو پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ پنجابی Foul Speech کے زمرے میں آتی ہے۔ Foul Speech جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک غیر شائستہ اور غیر مہذب رویہ ہے، اور ظاہر ہے کہ بیکن ہاؤس جیسا سسٹم اس غیر شائستگی اور تہذیب دشمنی کو کیسے برادشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اس سسٹم کے کرتا دھرتا لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجابی پر سرے سے پابندی ہی لگا دینی چاہیے۔
بیکن ہاؤس سکول سسٹم نے پنجابی میں گفتگو پر پابندی عائد کر دی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ پنجابی Foul Speech کے زمرے میں آتی ہے۔ Foul Speech جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک غیر شائستہ اور غیر مہذب رویہ ہے، اور ظاہر ہے کہ بیکن ہاؤس جیسا سسٹم اس غیر شائستگی اور تہذیب دشمنی کو کیسے برادشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اس سسٹم کے کرتا دھرتا لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجابی پر سرے سے پابندی ہی لگا دینی چاہیے۔
 اس عاجز کی خوش قسمتی کہ بچپن سے ہی عظیم لوگوں کی شفقت کا سلسلہ بڑے ابا (ناناجان) حکیم سید انصار الحق اور پھر ان کے چھوٹے بھائی نانا ابو حکیم ریاض حسین سے جاری ہوکر بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ مجھے زندگی میں ’بڑے انسان‘ دیکھنے کا موقع ملا۔ حضرت احمد جاوید وہ بزرگ ہیں جن کی شخصیت کا سب سے زیادہ خوشگوار اثر میرے دل و جان نے قبول کیا۔ باوجود چند گنی چنی ادب کے ساتھ مختلف آرا کے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ ان کے قدموں میں بارہا بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ قدرت یہ کام بھی لیتی گئی کہ آپ کے مبارک الفاظ نقل کرتا گیا، جو پیشِ خدمت ہیں۔ ان میں دنیا و آخرت، مادہ و روح، تنہائی و اجتماعیت ہر حوالے سے رہنمائی بھی موجود ہے اور تسکین کا سامان بھی۔ کہیں کوئی کجی نادانستگی سے رقم ہوجائے تو سب قصور میرا تصور ہوگا۔ چوں کہ ہر لائن ایک سمندر ہے لہذٰا ہر دفعہ ایک نشست کے تذکرے کی کوشش کی جائے گی۔ جو تبدیل ہونا چاہے تو وہ تبدیلی کے بےپناہ امکانات یہاں بکھرے پائے گا۔ ایک مؤمن کو کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اسلاف کیسے ہوتے ہوں گے؟ احمد جاوید کو دیکھ کر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ آج کی دنیا پہ قرض ہے کہ وہ اس عبقری سے فائدہ اٹھائے:
اس عاجز کی خوش قسمتی کہ بچپن سے ہی عظیم لوگوں کی شفقت کا سلسلہ بڑے ابا (ناناجان) حکیم سید انصار الحق اور پھر ان کے چھوٹے بھائی نانا ابو حکیم ریاض حسین سے جاری ہوکر بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ مجھے زندگی میں ’بڑے انسان‘ دیکھنے کا موقع ملا۔ حضرت احمد جاوید وہ بزرگ ہیں جن کی شخصیت کا سب سے زیادہ خوشگوار اثر میرے دل و جان نے قبول کیا۔ باوجود چند گنی چنی ادب کے ساتھ مختلف آرا کے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی شخصیت ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ ان کے قدموں میں بارہا بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ قدرت یہ کام بھی لیتی گئی کہ آپ کے مبارک الفاظ نقل کرتا گیا، جو پیشِ خدمت ہیں۔ ان میں دنیا و آخرت، مادہ و روح، تنہائی و اجتماعیت ہر حوالے سے رہنمائی بھی موجود ہے اور تسکین کا سامان بھی۔ کہیں کوئی کجی نادانستگی سے رقم ہوجائے تو سب قصور میرا تصور ہوگا۔ چوں کہ ہر لائن ایک سمندر ہے لہذٰا ہر دفعہ ایک نشست کے تذکرے کی کوشش کی جائے گی۔ جو تبدیل ہونا چاہے تو وہ تبدیلی کے بےپناہ امکانات یہاں بکھرے پائے گا۔ ایک مؤمن کو کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اسلاف کیسے ہوتے ہوں گے؟ احمد جاوید کو دیکھ کر معلوم کیا جاسکتا ہے۔ آج کی دنیا پہ قرض ہے کہ وہ اس عبقری سے فائدہ اٹھائے: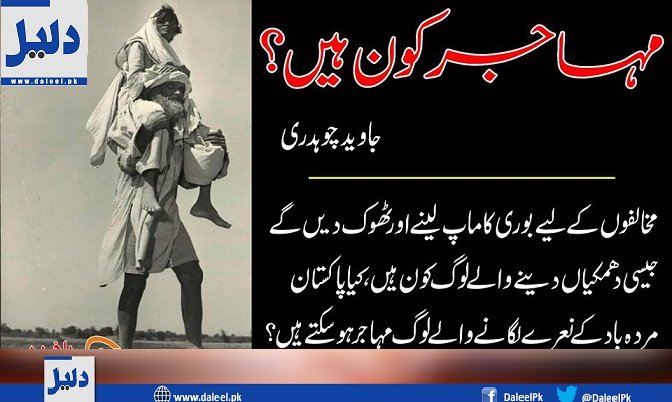




 نومبر ۱۹۸۹ء میں دیوارِ برلن کے گرنے کے ساتھ ہی بین الاقوامی سیاست میں سرد جنگ بھی اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد مغربی سیاست دانوں، پالیسی سازوں اور دانشوروں نے آئندہ اپنی خارجہ پالیسی کے لیے ایک نئی حکمت عملی وضع کی۔ اس تعلق سے سب سے پہلے ایک امریکی مفکر فرانسس فوکویاما نے ۱۹۸۹ء میں ایک امریکی رسالے The National Interest میں The End of History (انتہائے تاریخ) کے نام سے ایک مضمون لکھا کہ مغربی تہذیب انتہائی عروج پر ہے اور یہ ساری دنیا پر چھا جائے گی۔ اسی مضمون میں فوکویاما نے Liberal Democracy کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہی انسان کی نظریاتی ترقی کی آخری فتح ہے اور یہ کہ دنیا میں رائج نظریات کے درمیان کشمکش ختم ہوگئی ہے اور مغربی آزاد جمہوریت کے سوا اب دنیا میں کوئی نیا نظریہ یا نظام آنے والا نہیں ہے۔ ۱
نومبر ۱۹۸۹ء میں دیوارِ برلن کے گرنے کے ساتھ ہی بین الاقوامی سیاست میں سرد جنگ بھی اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد مغربی سیاست دانوں، پالیسی سازوں اور دانشوروں نے آئندہ اپنی خارجہ پالیسی کے لیے ایک نئی حکمت عملی وضع کی۔ اس تعلق سے سب سے پہلے ایک امریکی مفکر فرانسس فوکویاما نے ۱۹۸۹ء میں ایک امریکی رسالے The National Interest میں The End of History (انتہائے تاریخ) کے نام سے ایک مضمون لکھا کہ مغربی تہذیب انتہائی عروج پر ہے اور یہ ساری دنیا پر چھا جائے گی۔ اسی مضمون میں فوکویاما نے Liberal Democracy کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہی انسان کی نظریاتی ترقی کی آخری فتح ہے اور یہ کہ دنیا میں رائج نظریات کے درمیان کشمکش ختم ہوگئی ہے اور مغربی آزاد جمہوریت کے سوا اب دنیا میں کوئی نیا نظریہ یا نظام آنے والا نہیں ہے۔ ۱ مغر بی تہذیب جو اس وقت غالب تہذیب کی صورت اختیار کر چکی ہے، پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے۔ اس کا اسلامی تہذیب سے ہر حال میں تصادم ہونا ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے‘‘۔ ہن ٹنگٹن نے ۱۹۹۳ء کے فارن افیئرز میں The Clash of Civilizations کے عنوان سے مضمون لکھا، جسے ۱۹۹۶ء میں پھیلا کر The Clash of Civilizations and Remaking of the New World Order (تہذیبوں کا تصادم اور نئے عالمی نظام کی تشکیل) کے نام سے کتابی شکل میں شائع کیا، اور پھر اس پر دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر مباحثے کا آغاز ہوا۔ نائن الیون کے بعد اس مباحثے نے نہ صرف طول پکڑا بلکہ شدت بھی اختیار کر لی۔
مغر بی تہذیب جو اس وقت غالب تہذیب کی صورت اختیار کر چکی ہے، پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے۔ اس کا اسلامی تہذیب سے ہر حال میں تصادم ہونا ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے‘‘۔ ہن ٹنگٹن نے ۱۹۹۳ء کے فارن افیئرز میں The Clash of Civilizations کے عنوان سے مضمون لکھا، جسے ۱۹۹۶ء میں پھیلا کر The Clash of Civilizations and Remaking of the New World Order (تہذیبوں کا تصادم اور نئے عالمی نظام کی تشکیل) کے نام سے کتابی شکل میں شائع کیا، اور پھر اس پر دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر مباحثے کا آغاز ہوا۔ نائن الیون کے بعد اس مباحثے نے نہ صرف طول پکڑا بلکہ شدت بھی اختیار کر لی۔ ماہرین نے تہذیبوں کا گہرائی سے مطالعہ پیش کیا ہے۔ مشہور مؤرخ ٹائن بی نے پہلے ۲۱ اور بعد میں دنیا کو ۲۳ تہذیبوں میں تقسیم کیا۔ اسپنگر نے دنیا کی آٹھ بڑی ثقافتوں کی نشان دہی کی، میک نیل نے تہذیبوں کی تعداد ۹بتائی، سلکیو نے ۱۲تہذ یبوں کی نشان د ہی کی ہے ۶، جبکہ خود ہن ٹنگٹن نے دنیا کی آٹھ بڑی تہذیبوں کا تذکرہ کیا اور کہا ہے کہ مستقبل میں تصادم انھی تہذیبوں کے درمیان ہوگا : ۱۔چینی ( کنفیوشس) ۲۔ جاپانی ۳۔ ہندو۴۔ اسلامی۵۔ قدامت پرست عیسائی ۶۔ لاطینی ۷۔ افر یقی۸۔ مغر بی تہذ یب۔
ماہرین نے تہذیبوں کا گہرائی سے مطالعہ پیش کیا ہے۔ مشہور مؤرخ ٹائن بی نے پہلے ۲۱ اور بعد میں دنیا کو ۲۳ تہذیبوں میں تقسیم کیا۔ اسپنگر نے دنیا کی آٹھ بڑی ثقافتوں کی نشان دہی کی، میک نیل نے تہذیبوں کی تعداد ۹بتائی، سلکیو نے ۱۲تہذ یبوں کی نشان د ہی کی ہے ۶، جبکہ خود ہن ٹنگٹن نے دنیا کی آٹھ بڑی تہذیبوں کا تذکرہ کیا اور کہا ہے کہ مستقبل میں تصادم انھی تہذیبوں کے درمیان ہوگا : ۱۔چینی ( کنفیوشس) ۲۔ جاپانی ۳۔ ہندو۴۔ اسلامی۵۔ قدامت پرست عیسائی ۶۔ لاطینی ۷۔ افر یقی۸۔ مغر بی تہذ یب۔ اسلام اور عیسائیت، مسیحی اور مغربی دونوں کے درمیان تعلقات اکثر ہنگامہ خیز رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہے ہیں۔ آزاد جمہوریت اور مارکسی لنین ازم کے درمیان انیسویں صدی کا تنازع اسلام اور عیسائیت کے درمیان مسلسل اور گہرے مخاصمانہ تعلقات کے مقابلے میں ایک عارضی اور سطحی مظہر ہے۔۱۰ ہن ٹنگٹن کو معلوم تھا کہ مغرب، اسلام کے خلاف سیاسی پروپیگنڈے اور سیاسی سازشوں سے زیادہ دیر تک عالم اسلام میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا اور نہ فوجی اور اقتصادی بنیادوں پر باقی دنیا کو اپنے پنجۂ استبداد میں رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اسلام اور اس کی تہذیب کو مغرب کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا:
اسلام اور عیسائیت، مسیحی اور مغربی دونوں کے درمیان تعلقات اکثر ہنگامہ خیز رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہے ہیں۔ آزاد جمہوریت اور مارکسی لنین ازم کے درمیان انیسویں صدی کا تنازع اسلام اور عیسائیت کے درمیان مسلسل اور گہرے مخاصمانہ تعلقات کے مقابلے میں ایک عارضی اور سطحی مظہر ہے۔۱۰ ہن ٹنگٹن کو معلوم تھا کہ مغرب، اسلام کے خلاف سیاسی پروپیگنڈے اور سیاسی سازشوں سے زیادہ دیر تک عالم اسلام میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا اور نہ فوجی اور اقتصادی بنیادوں پر باقی دنیا کو اپنے پنجۂ استبداد میں رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اسلام اور اس کی تہذیب کو مغرب کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا: