میرے مضمون ’’قرآن میں لفظ ’’مشرک ‘‘ کا استعمال واطلاق ‘‘ کو جن لوگوں نے سراہا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بدھلہ ملتان سے میرے ایک دوست عدنان قاسم صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک ایسے دور میں جب ہزاروں کی تعداد میں غلط روایات کو اسلامی رنگ دے کر پروان چڑھایا جارہا ہو اور اس کے لیے دلائل بھی غلط احادیث اور ان کی غلط تشریحات سے دیے جا رہے ہوں اور کوئی اس کی وجہ سے انجانے میں شرک کا مرتکب ہو رہا ہو جبکہ دل میں کجی یا ٹیڑ ھ بھی نہ ہوجبکہ اس کو تبلیغ بھی نہ کی گئی ہو تو کیا ان لوگوں کو بھی کافر ومشرک کہا جائے گا یا کوئی توقف کیا جائے گا؟
جواب: دلوں کا حال اللہ جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے ؟ ہم اس کے لیے مکلف نہیں ہیں۔ آخرت کا معاملہ الگ ہے اور دنیا کا معاملہ الگ ۔ آخرت کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں فیصلہ ظاہر پر کیا جاتا ہے نہ کہ کسی کے دل میں پوشیدہ باتوں پرجن کا ہمیں علم تک نہ ہو۔ اب اگرکوئی شخص بظاہر ایمان لا کراسلام قبول کرے تو اسے مومن یا مسلم کہا جائے گا خواہ اس کے دل میں کفر ،شرک یا نفاق کیوں نہ چھپا ہو اورایسا شخص جو بظاہر ایمان نہ لائے اور اسلام قبول نہ کرے تو اس کو مومن یا مسلم تسلیم نہیں کیا جاسکتا خواہ وہ اپنے دل میںایمان کیوں نہ رکھتا ہو۔ ہم ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں اور ظاہر ہی پر فیصلہ کرسکتے ہیں نہ کہ باطن پر ۔ باطن کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب جو شخص ایمان نہ رکھتا ہو اور دائرہٗ اسلام سے باہر ہو اور شرک میں ملوث ہو اگر اس سے انجانے میں شرک ہورہا ہو یا وہ جان بوجھ کر شرک کررہا ہو خواہ غلط روایات یا غلط تشریحات کی بنا پر کیوں نہ ہو لیکن ظاہری طو رپرتو وہ شرک کا مرتکب ہورہا ہے اورشرک جو ظلم ِ عظیم ہے ِ اللہ تعالیٰ کے ہاںا س کی بخشش نہیں۔ اس نے اس قبیح اور ناقابل معافی جرم کی سزا جہنم بتائی ہے اور ارشاد فریاما:
[pullquote]اِنَّہٗ مَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰہِ فَقَدْحَرَّ مَ اللّٰہُ عَلَیْہِ الْجَنَّۃَ وَمَاْوٰہٗ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارِ[/pullquote]
ترجمہ: ’’بے شک جس نے اللہ کے سا تھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کیا ہے اور اس کاٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں‘‘ ( سورہ الما ئدۃ آیت نمبر۷۲)
اللہ کے آخری رسول محمد ﷺ نے فرمایا ہے:
[pullquote]من مات یشرک باللہ شیئاً دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئاً دخل الجنۃ (مسلم) [/pullquote]
ترجمہ : ۔ ’’ جو شخص اس حالت میں مر جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتا ہے آگ میں داخل ہوگا اور جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا‘‘۔
[pullquote]إنَّ اللہ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَکَ بِہِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاء ُ وَمَن یُشْرِکْ بِاللہ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیْدا (سورۃ النساء آیت نمبر ۱۱۶)[/pullquote]
ترجمہ :۔’’بے شک اللہ یہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو جس کے لئے چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی دور جا پڑا ۔
اب آپ غور کریں ان آیات میں یہ ذکر نہیں کہ اس سے یہ شرک انجانے سے ہوا یااس نے جانتے بوجھتے کیا لیکن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا ۔اس کو آپ ظلم بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ عدل کرنے والاہے ،اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ۔وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا کہ کسی کو بلاوجہ سزا دے گا کیونکہ اس نے انسان کو اس کے پیدا ہونے سے قبل اس کی فطرت میں توحید کا عقیدہ ڈال دیا تھا اور ازل ہی سے یہی عقیدہ سے اس کی سرشت اوراس کے شعور میں پیوست کردیا تھا اور تمام انسانوں سے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمھارا رب نہیں ہوں اور سب نے یہ اقرار کیا تھا کہ آپ واقعی ہمارے رب ہیںاو ر پھر اللہ نے توحید کایہی عہدواقرار اس کی فطرت کے اندودیعت فرمایا اور پھر اسی فطرت پر انسانوں کی پیدائش فرمائی، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے :
[pullquote]فاقِمْ وَجْہَکَ لِلدِّیْنِ حَنِیْفاً فِطْرَۃَ اللہ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْْہَا (سورۃ الروم ۳۰ آیت نمبر۳۰)[/pullquote]
ترجمہ: پس آپ یکسو ہوکر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں ،اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیاہے ۔
اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ
[pullquote]ما من مولود یولد علی الفطرۃ ۔ (بخاری ومسلم )[/pullquote]
چونکہ پہلے ہی سے انسان کے عقل وشعور ،اس کی سرشت اور اس کی جبلت اور اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ،الوہیت اور توحید کے عقیدے کا علم موجود ہے اس لیے اس سے اس کی بے خبری یا لاعلمی کا عذرقابل قبول نہیں اور تقریباً تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ازل ہی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میںتوحید کا عقیدہ ودیعت کردیا ہے ملاحظہ ہوں مختصراً چند مفسرین کے اقوال:
1. ’’ یعنی تمام انسان اس فطرت پر پیدا کئے گئے ہیں کہ ان کا کوئی خالق اور کوئی رب اور کوئی معبود اور مطاع حقیقی ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔‘‘ (تفہیم القرآن جلد سوم )
2. ’’ فطرت کے اصل معنی خلقت (پیدائش ) کے ہیں ۔ یہاں مراد ملت اسلام (وتوحید ) ہے مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش،بغیر مسلم وکافر کی تفریق کے اسلام اور توحید پر ہوئی ہے، اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی جبلت میں شامل ہے جس طرح عہد الست سے واضح ہے ۔‘‘ (تفسیر احسن البیان صفحہ ۹۵۶)
3. ’’رب کی فطرت سلیمہ پر وہی قائم ہے جو اس دین اسلام کا پابند ہے۔ اسی پر یعنی توحید پر رب نے تمام انسانوں کو بنایا ہے۔ روز اول میں اسی کا سب سے اقرار کر لیا گیا تھا کہ کیا میں سب کا رب نہیں ہوں ؟ تو سب نے اقرار کیا کہ بیشک تو ہی ہمارا رب ہے ۔‘‘ (ابن کثیر اردو جلد چہارم صفحہ ۱۷۷)
4. ’’یعنی ہر طرف سے کٹ کر اس دین فطرت کی پیروی کرو جس پر فاطر فطرت نے لوگوں کو پیدا کیا ہے‘‘۔ ’’یہ دین خارج کی کوئی چیز نہیں ہے جو تم پر اوپر سے لادی جا رہی ہو، بلکہ یہ عین تمھاری فطرت کا بروز اور تمھارے اپنے باطن کا خزانہ ہے جو تمھارے دامن میں ڈالا جا رہا ہے۔‘‘ ’’انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت اور بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے ۔ اس کو خیر وشر اور حق وباطل کی معرفت عطا فرمائی ہے اور نیکی اور بدی کا جزبہ بھی اس کے اندر ودیعت فرمایا ہے ۔‘‘ (تدبر قرآن جلد ششم صفحہ ۹۴)
5. ’’اللہ کی فطرت (یعنی دین اسلام کو) جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ۔‘‘ یعنی تمام لوگوں کے اند ر صلاحیت اور استعداد پیدا کردی ہے کہ فطرت کو جان سکتے ہیں اور اس پر چل سکتے ہیں، گویا فطرت سے مراد ہے فطری استعداد جو ہر شخص میں پیدائشی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک فطرت سے وہ وعدہ مراد ہے جو اللہ نے حضرت آدم اور آپ کی ساری نسل سے لیا تھا اور فرمایا تھا: الست بربکم، کیا میں تمھارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلیٰ تو سب نے جواب دیا: کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اسی ازلی اقرار پر پیدا ہوتا ہے ۔یہ ہی حنیفیت ہے جس پر سارے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے ۔یعنی ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سالم سرشت لے کر آتا ہے، اس کی طبیعت قبول حق کے لیے تیار ہوتی ہے۔‘‘ ( تفسیر مظہری جلد نہم صفحہ ۱۵۳)
6. ’’فطرت اللہ سے اللہ کی توحید مراد ہے جس کی قابلیت واستعداد اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کی فطرت اور خلقت میں ودیعت فرمائی۔‘‘ (جواہر القرآن جلد سوم صفحہ ۸۹۷)
7. ’’یہ بات ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ اس کا خالق ومالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اس کا بندہ اور غلام ہے ۔لہٰذا اسے صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہئیے ۔چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت (اسلام ) پر پیدا ہوتا ہے ۔‘‘ ’’ بالفاظ دیگر ہر انسان کی فطرت میں قبول حق کی استعداد رکھ دی گئی ہے اور اسی لیے قبول حق کا مکلف بھی بنایا گیا ہے ۔‘‘ (تیسیر القرآن جلد سوم صفحہ ۵۱۳)
یہ بات تو دو اور دو چار کی طرح واضح ہو ئی کہ توحید کا عقیدہ ،حق وباطل اور خیر وشر کی پہچان رو ز ازل ہی سے انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے اورہرانسان کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے، اس میں قبول حق کی استعدا د رکھ دی گئی ہے اور اسی لیے اسے قبول حق کا مکلف بنایا گیا ہے ۔ اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی صلاحیت کو بروئے کار نہ لائے اور خود کو بے خبر رکھے ۔تو اس کا یہ عذر قیامت کے دن قابل قبول نہ ہوگا ۔ آئیے مزید وضاحت کے لیے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ۱۷۲ اور ۱۷۳ پر نظر ڈالتے ہیں�،
[pullquote] وَإذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِیْ آدَمَ مِن ظُہُورِہِمْ ذُرِّیَّتَہُمْ وَأَشْہَدَہُمْ عَلَی أَنفُسِہِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُواْ بَلَی شَہِدْنَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ إِنَّا کُنَّا عَنْ ہَذَا غَافِلِیْنَ (172) أَوْ تَقُولُواْ إنَّمَا أَشْرَکَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَکُنَّا ذُرِّیَّۃً مِّن بَعْدِہِمْ أَفَتُہْلِکُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (سورۃ الاعراف۷ آیت نمبر ۱۷۲ ،۱۷۳[/pullquote]
ترجمہ: اور جب تمھارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا : کیا میں تمھارا رب نہیں ہوں ؟ انہوں نے جواب دیا : ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں ،ہم اس پر گواہی دیتے ہیں ۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دینا کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے ۔یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے ۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟
اس بات پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس عہد [pullquote]’’أَلَسْتُ بِرَبِّکُم قَالُواْ بَلَی شَہِدْنَا‘‘[/pullquote]
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے معاملے میں تمام بنی نوع انسان پر اتمام حجت ہوچکی ہے ۔انہیں اور کسی مزیددعوت وتبلیغ کی حاجت نہیں ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب جو تکفیر کے جواز کے قائل نہیں اور ان کے نزدیک انقطاع وحی کے بعد دنیا کے کسی بھی فرد ( خواہ وہ عیسائی ، یہودی،مجوس، صابی ،ہندو ، سکھ یا بدھ مت والے کیوں نہ ہو) کو اس کے کفر یا شرک کی بنا پر کافر یا مشرک قرار نہیں دیا جاسکتا اور اس کی تکفیر کو غلط کہتے ہیںخود بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرسکے اور اپنی تفسیر ’’البیان‘‘ میں لکھا :
’’جہاں تک توحید اور بدیہات فطرت کا تعلق ہے ،ان کے بارے میں مجرد اس اقرار کی بنا پر بنی آدم کا مواخذہ کیا جائے گا ۔ان سے انحراف کے لیے کسی کا یہ عذر خدا کے ہاں مسموع نہ ہوگا کہ اسے کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی یا اس نے یہ انحراف خارجی اثرات کے نتیجے میں اختیار کیا تھا اور اس کے ذمہ دار اس کے باپ دادا اور اس کا ماحول ہے۔قرآن کا ارشاد ہے کہ انسان کے باطن کی یہ شہادت ایسی قطعی ہے کہ ہر شخص مجرد اس شہادت کی بناپر اللہ کے حضور میں جواب دہ ہے۔ مزید حجت جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ان کا مواخذہ کیا جائے گا اور آخرت کے لحاظ سے بھی ان کی مسئو لیت دوچند ہو جائے گی ،ورنہ اصلاً تو یہ حجت،جیسا کہ بیان ہو ا، اس علم سے قائم ہو جاتی ہے جوانسان کے فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے ۔‘‘ (البیان جلد دوم صفحہ ۲۴۲ ،۲۴۳ حاشیہ نمبر ۵۶۶ ، ۵۶۷)
یعنی عقیدۂ توحید کاعلم ازل ہی سے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اس لیے وہ بے خبر نہیں۔لہٰذا قیامت کے روز وہ اپنی لاعلمی یا بے خبری کاعذر پیش نہیں کرسکے گا ۔غامدی صاحب لکھتے ہیں :
’’زمین پر خدا کی دینونت کے واقعات سے استدلال کے بعد اب یہ قریش کو اس عہد فطرت کی یاددہانی کرائی ہے جس کی بنیاد تمام بنی آدم قیامت کے دن مسئول ٹھیرائے جائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اسے کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی یا اس نے شرک اور الحاد کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور خدا کے اقرار اور اس کی توحیدکے تصور تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن تھا ۔ قرآن نے اس عہد کو جس طریقے سے پیش کیا ہے ،اس سے واضح ہے کہ یہ محض تمثیلی انداز بیان نہیں ہے بلکہ اسی طرح کے ایک واقعے کا بیان ہے جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں ۔اس سے یہ حقیقت مبرہن ہوجاتی ہے کہ خالق کا اقرار مخلوقات کی فطرت ہے ۔‘‘
اصل الفاظ ہیں: مِن بَنِیْ آدَمَ مِن ظُہُورِہِمْ ۔ مِن ظُہُورِہِمْ مِن بَنِیْ آدَمَ سے بدل واقع ہوا ہے۔ اس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کسی خاص دور ہی کے بنی آدم سے متعلق نہیںبلکہ قیامت کے دن تک جتنے بنی آدم بھی پیدا ہونے والے ہیں ،ان سب سے متعلق ہے اور ارواح کے اجسام کے ساتھ اتصال کی ابتدا سے پہلے ہوا ۔‘‘ (البیان جلد ۲ صفحہ ۲۴۱ )
جناب امین احسن اصلاحی صاحب اپنی تفسیر ’’تدبر قرآن‘‘ میں لکھتے ہیں :
اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ہے اور وہ اس طرح کہ اس نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا میں تمھارا رب نہیں ہوں ، اس کے جواب میں سب نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں ۔یہ ملحوظ رہے کہ الفاظ سے یہ بات واضح ہے کہ یہ اقرار اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات کا نہیں لیا کہ وہ اللہ ہے بلکہ اس بات کا لیا کہ وہی رب بھی ہے ۔یہ ملحوظ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اہل عرب کو اللہ کے اللہ ہونے سے انکار نہیں تھا لیکن رب انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی بنا لیے تھے حالانکہ عہد فطرت میں اقرار صرف اللہ ہی کی ربوبیت کا ہے۔ (تدبر قرآن جلد سوم صفحہ ۳۹۲ ،۳۹۳)‘‘
یہی بات سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب قدرے تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’جیسا کہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے ،یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پرپیش آیا تھا ۔اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کرکے انسان اول کو سجدہ کرایا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا،اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی، جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالی نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابی ّ بن کعب نے غالباً نبی ﷺ سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس مضمون کی بہترین شرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں:
’’اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا او ر ( ایک ایک قسم یا ایک ایک دورکے) لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی ، پھر ان سے عہد ومیثاق لیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمھارا رب نہیں ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پرزمین وآسمان سب کو اور خود تمھارے باپ آدم کو گواہ ٹھیراتا ہوں تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کوعلم نہ تھا۔خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانا ۔ میں تمھارے پاس اپنے پیغمبربھیجوں گا جو تم کو یہ عہد و میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو ،یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے ، آپ ہی ہماے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں ، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود ۔‘‘
اس معاملہ کو بعض لوگ محض تمثیلی انداز بیاں پر محمول کرتے ہیں ۔ان کا خیال یہ ہے کہ دراصل یہاں قرآن مجید صرف یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست ہے اور اس بات کو یہاں ایسے انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا یہ ایک واقعہ تھا جو عالم خارجی میں پیش آیا۔ لیکن ہم اس تاویل کو صحیح نہیں سمجھتے ۔ قرآن اور حدیث دونوں میں اسے بالکل ایک واقعہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور صرف بیان واقعہ پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے روز بنی آدم پر حجت قائم کرتے ہوئے اس ازلی عہد واقرار کو سند میں پیش کیا جائے گا ۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے محض ایک تمثیلی بیان قرار دیں ۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا تھا جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع ان تمام انسانوں کو جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے کاارادہ رکھتا تھا ،بیک وقت زندگی اور شعور اور گویائی عطا کرکے اپنے سامنے حاضر کیا تھا، اور فی الواقع انہیں اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ کردیا تھا کہ ان کا کوئی رب اور کوئی الٰہ اس کی ذات اقدس واعلیٰ کے سوا نہیں ہے ،اور ان کے لیے کوئی صحیح طریق زندگی اس کی بندگی وفرمان برداری (اسلام) کے سوا نہیں ہے ۔‘‘
’’اس آیت میں وہ غرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسل آدم سے اقرار لیا گیا تھا ۔اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کے پوری طرح ذمہ دار قرار پائیں۔ وہ اپنی صفائی میں نہ تولاعلمی کا عذر پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ وہ سابق نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری الذمہ ہو سکیں گویا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ اس ازلی عہد ومیثاق کو اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے کہ نوع انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الٰہ واحد اور رب واحد ہونے کی شہادت اپنے اندرلیے ہوئے ہے اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے،یا ایک گمراہ ماحول میںپرورش پانے کے سبب سے اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بالکلیہ بری ہو سکتا ہے ۔‘‘ ( تفہیم القران جلد دوم صفحہ۹۶ ،۹۷ حاشیہ نمبر ۱۳۴ ،۱۳۵)
ان تصریحات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا عقیدہ ازل ہی سے تمام انسانوں کی فطرت میں رکھ دیاگیا ہے ۔ اور ازل ہی سے اس کاعلم ان کی فطرت میں ودیعت کیاگیا ہے اس لیے وہ اس سے بے علم یا بے خبر نہیں۔ ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الٰہ واحد اور رب واحد ہونے کی شہادت اپنے اندرلیے ہوئے ہے ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کرسکے گا کہ اسے کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی یا اس نے شرک اور الحاد کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی اور خدا کے اقرار اور اس کی توحیدکے تصور تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن تھا ۔اب آپ کا یہ سوال کہ ایسے لوگ جن کو توحید کی دعوت نہ پہنچی ہو اور وہ انجانے سے شرک میں ملوث ہو، ایک مفروضہ تو ہو سکتا ہے ،حقیقت نہیں ۔ اول تو یہ بات بعید از قیاس ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کواسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ آج دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے جس کے کونے کونے تک کسی نہ کسی طرح اسلام کا پیغام پہنچ گیا ہے ،دوم اور اگر بالفرض محال کہیں دور دنیا سے الگ تھلگ کسی علاقے میں ایسا کوئی شخص موجود بھی ہو جو مسلمانوں کے ماحول ، معاشرے اور ملک سے باہرہو اور ان کااس سے کوئی تعلق یا واسطہ نہ ہو اور اس کے بارے میں مسلمانوں کو کوئی خبر بھی نہ ہو تو مسلمان اس بات کے مکلف نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں ۔اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کے بارے اپنافیصلہ صادر فرمائے گا ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق ؑعطا فرمائے!


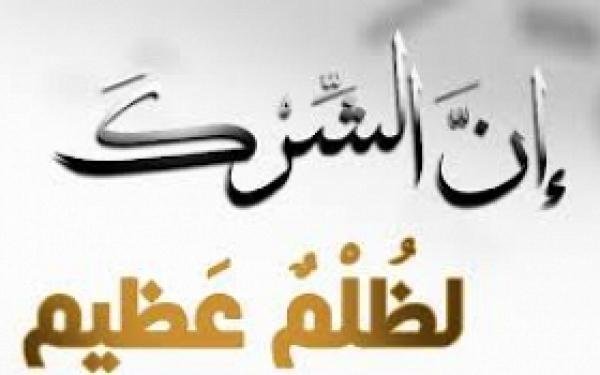

 گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے لبرل دانشوروں کو کوئی اور پرکشش موضوع ہاتھ نہ آئے تو مذہب اور اہلِ مذہب کی خبر گیری اور اصلاح کے درپے ہوجاتے ہیں۔ وہ یہ باور کراتے ہیں کہ ہماری تمام تر ناکامیوں اور زوال کے ذمے دار مذہبی طبقات ہیں اور مذہب ہی ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ پھر اچانک انہیں خیال آتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اورجمود طاری ہے، حالانکہ علامہ اقبال نے کہا تھا: اجتہاد جاری رہنا چاہیے۔
گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے لبرل دانشوروں کو کوئی اور پرکشش موضوع ہاتھ نہ آئے تو مذہب اور اہلِ مذہب کی خبر گیری اور اصلاح کے درپے ہوجاتے ہیں۔ وہ یہ باور کراتے ہیں کہ ہماری تمام تر ناکامیوں اور زوال کے ذمے دار مذہبی طبقات ہیں اور مذہب ہی ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ پھر اچانک انہیں خیال آتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اورجمود طاری ہے، حالانکہ علامہ اقبال نے کہا تھا: اجتہاد جاری رہنا چاہیے۔
 زندگی کے تیزی سےگزرتے شب و روز میں کسی رات سونے کے لیے نرم و ملائم بستر پر لیٹ کر کبھی ہمیں یہ غور کرنے کا وقت ملا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا میں اپنی مرضی سے یہاں تک پہنچا ہوں اور کیا اپنی مرضی سے یہ دنیا چھوڑ کر جاؤں گا؟
زندگی کے تیزی سےگزرتے شب و روز میں کسی رات سونے کے لیے نرم و ملائم بستر پر لیٹ کر کبھی ہمیں یہ غور کرنے کا وقت ملا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا میں اپنی مرضی سے یہاں تک پہنچا ہوں اور کیا اپنی مرضی سے یہ دنیا چھوڑ کر جاؤں گا؟


 1۔ اسلامی قانون کی رو سے قتلِ خطا کی صورت میں دیت کی ادائیگی لازم ہے، الا یہ کہ مقتول کے ورثا اسے کلی یا جزوی طور پر معاف کردیں۔
1۔ اسلامی قانون کی رو سے قتلِ خطا کی صورت میں دیت کی ادائیگی لازم ہے، الا یہ کہ مقتول کے ورثا اسے کلی یا جزوی طور پر معاف کردیں۔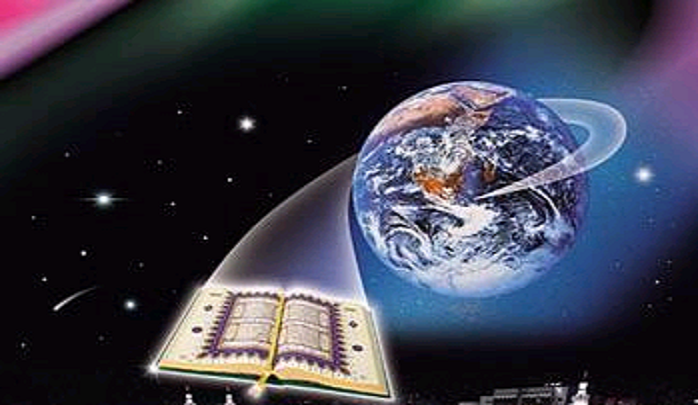
 مستشرقین (Orientalists) قرآن کریم کے مقابلے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ ان کی دلچسپی تاریخ اور سیرت کا از سر نو ترتیب کرنے میں ہے، جس کا اظہار ہارلڈ موتزکی نے اپنی کتاب ((Dating Muslim tradition میں کیا ہے، اور ان دونوں کی تحقیق کے لیے قرآن بحثیت مصدر ناکافی ہے، اس لیے مجبورا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و سلم سے رجوع کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ گریگر شیلر، ہارلڈ مو تزکی، اور اینڈریس گورک کی تحقیق ونظریہ ہے-
مستشرقین (Orientalists) قرآن کریم کے مقابلے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ ان کی دلچسپی تاریخ اور سیرت کا از سر نو ترتیب کرنے میں ہے، جس کا اظہار ہارلڈ موتزکی نے اپنی کتاب ((Dating Muslim tradition میں کیا ہے، اور ان دونوں کی تحقیق کے لیے قرآن بحثیت مصدر ناکافی ہے، اس لیے مجبورا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و سلم سے رجوع کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ گریگر شیلر، ہارلڈ مو تزکی، اور اینڈریس گورک کی تحقیق ونظریہ ہے-
 اللہ کے نبی – صلى اللہ عليہ وسلم – کا فرمان ہے کہ:
اللہ کے نبی – صلى اللہ عليہ وسلم – کا فرمان ہے کہ: