 جہانگیر بدر انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
جہانگیر بدر انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
سپریم کورٹ میں بھٹو ریفرنس کی سماعت ہو رہی تھی. مجھے بھی اس کیس میں وفاق کی جانب سے معاون وکیل مقرر کیا گیا تھا، اس لیے ہر سماعت پر میں سپریم کورٹ میں موجود ہوتا تھا.
ایک روز جب سماعت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کے وزیر راجہ ریاض کے بھائی راجہ نعیم نے مجھے کہا کہ پیچھے چلو تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں.
میں ان کے ساتھ اٹھ کر پیچھے آگیا.
جہانگیر بدر کو دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا. لیکن وہ خود جہانگیر بدر کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے. ان کے نظریں سامنے ججز کی نشستوں کی طرف تھیں.
جی دیکھ رہا ہوں.
وہ کیا کر رہے ہیں؟
ٹیب پر کچھ پڑھ رہے ہیں.
جہانگیر بدر ٹیب پر کچھ پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ جیسے کتاب کا صفحہ الٹتے ہیں ویسے ہی ٹیب پر آگے بڑھتے جا رہے تھے.
غور سے دیکھیں، نعیم نے کہا، وہ ٹیب کو انگلی سے آپریٹ کر رہے ہیں یا انگوٹھے سے؟
انگوٹھے سے……. . میں نے انہیں بتایا.
کیا وہ ساتھ ساتھ انگوٹھے پر تھوک بھی لگا رہے ہیں؟
میں نے دیکھا وہ تھوڑی دیر بعد انگوٹھے کو زبان پر لگاتے اور پھر ٹیب پر گھماتے لگتے. یہ ایسے ہی تھا جیسے بعض لوگ نوٹ گنتے گنتے انگلی زبان سے لگا کر گیلی کرتے ہیں.
ہاں لگا رہے ہیں.
نعیم نے مسکراتے ہوئے کہا : بس یہی دکھانا تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
خود بتاؤں یا انہی سے پوچھ کر بتاؤں؟
ان سے پوچھ کے بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے. نعیم نے جواب دیا اور ہم دونوں قہقہہ لگا کر خاموش ہو گئے. ججز کمرہ عدالت میں داخل ہو چکے تھے.
کچھ دن بعد سپریم کورٹ بار روم میں کچھ وکلاء کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی، جہانگیر بدر بھی موجود تھے. ماحول خاصا خوشگوار اور بےتکلف تھا. میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا قصہ سنا کر پوچھ لیا. جہانگیر بدر َصاحب خلق خدا اب یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ ٹیب کو تھوک کیوں لگاتے ہیں.
قہقہے پھوٹ پڑے لیکن سب سے اونچا قہقہہ جہانگیر بدر صاحب کا تھا.
تکلفات اور تصنع سے قدرے بے نیاز ایک سادہ اور جینیوئن جہانگیر بدر مجھے ہمیشہ اچھے لگے. سرمایہ دارانہ سیاست میں وہ کارکن سیاست کی چند نشانیوں میں سے ایک تھے. بھٹو مرحوم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ مجبوریوں کے ساتھ ساتھ عوامی رومان کو کسی حد تک زندہ رکھا اور جہانگیر بدر جیسے غریب کارکن کو بھی عزت دی.
جہانگیر بدر نے بھی اس عزت کی لاج رکھی. دھوپ چھاؤں زندگی کا حصہ ہے، جہانگیر بدر ہر دو صورتوں میں اپنی جماعت کے ساتھ رہے.
اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین
Category: شخصیات
-

جہانگیر بدر انتقال کر گئے – آصف محمود
-

ظفر جمال بلوچ مرحوم کے نام -اصغر عبداللہ

یہ گزشتہ جون کاکوئی آخری دن تھا۔ معلوم ہواکہ اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم اعلیٰ ظفرجمال بلوچ طویل علالت کے بعد شیخ زاید اسپتال میں انتقال فرماگئے ہیں۔ یہ خبرسنتے ہی ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہواکہ جیسے دل کے اندرہی اندرکوئی چیزایک چھماکے کے ساتھ ٹوٹ کے گری ہے۔
گزشتہ روزسہ پہرکومنصورہ ان کے جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچاتوپتا چلاکہ مجھے تاخیر سے اطلاع ملی ہے۔ ان کاجسدخاکی ایک روز پہلے ہی جھنگ لے جایا جاچکا تھا، جہاں ان کوسپردخاک بھی کردیا گیا تھا۔ میں نے برادرمکرم سلیم منصورخالدکوفون کیااوران کے ساتھ ہی تعزیت کرکے دل کا بوجھ ہلکا کیااورواپس آگیا۔
ظفرجمال بلوچ کے ساتھ ذاتی طورپرمیری کوئی قربت نہیں تھی، مگران کے نام اورکام کے ساتھ اسکول کے زمانے سے ہی اس طرح کی شناسائی پیداہو گئی کہ ان سے دور رہ کربھی ہمیشہ ان سے ایک گوناقربت کااحساس رہا۔ شروع سردیوں کی وہ شام مجھے آج بھی یاد ہے۔ گجرات گھرکے دروازے پرکسی نے دستک دی۔ باہر نکلاتواسلامی جمعیت طلبہ کے سرگرم کارکن سیدحسنات احمداپنی دل آویز مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ ان کے عقب میں مشتاق فاروقی صاحب نے اسکول کی دیوارکے ساتھ ٹیک لگا رکھی تھی اورعینک اتارکراس کے شیشے صاف کررہے تھے۔ حسنات میرے ہم عمرطالب علم تھے اوربعدمیںان سے بڑی گہری دوستی بھی ہوگئی۔
مشتاق فاروقی صاحب مگرہم دونوں سے کافی سینئرتھے اوران دنوں نشترمیڈیکل کالج ملتان میں ایم بی بی ایس کے طالب علم تھے۔ خیر، ادھر ادھر کی باتوں کے انھوںنے دوپمفلٹ مجھے پڑھنے کے لیے دیے ’سلامتی کاراستہ‘ جومولانا مودوی کالکھا ہوا تھا اور ’خالدکے نام‘جس پرظفرجمال بلوچ کانام بطورمصنف درج تھا۔ یہ خطوط انھوں نے جیل سے اپنے کسی بچپن کے دوست خالدکے نام لکھے تھے۔ ان دنوں زنداں نامے پڑھنے کا ویسے ہی بڑاکریزتھا۔ میں نے بھی یہ خطوط بڑی دلچسپی سے پڑھے۔
سرورق پران کی تصویرنہیں تھی۔مگران کے نام اور بھٹودورکی طلبہ تحریکوں میں ان کے کردارکے پس منظرمیں ان کاجوسراپاذہن میں ابھرتا تھا، وہ کسی بھاری بھرکم بلوچ نوجوان سردارکاتھا۔ پہلی بارجب میں نے ان کوجمعیت کے ایک جلسے میں دیکھاتوسخت مایوسی ہوئی کیونکہ ان کااصل سراپااس کے بالکل برعکس تھے، درمیانہ سا قد، منحنی سا بدن، معمولی نقش ونگاراورعام سادہ سا لباس۔ تاہم بعدمیں جب ان کی تقریرسنی اوران کے ساتھ کچھ گفتگو کا موقع ملاتومحسوس ہوا کہ اس نحیف ونزاربدن میں واقعی ایک شعلہ جوالہ بھڑک رہاہے۔
ظفرجمال بلوچ نے1949ء میں ضلع جھنگ کے گاوںچک 175میں آنکھ کھولی۔ان کے والدبائیں بازوکے خیالات رکھنے والے آدمی تھے۔ابتدائی تعلیم غازی آباداورجھنگ صدرسے پائی۔اسلامیہ ہائی اسکول جھنگ سے میٹرک اورگورنمنٹ کالج جھنگ سے گریجویشن کی۔ بعد ازاں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1966 میں جمعیت کے رکن بنے۔ مغربی پاکستان یونٹ کے جنرل سیکریٹری اور بعدمیںصوبہ پنجاب کے ناظم رہے۔
16ستمبر1972ء کو تسنیم عالم منظرکی شہادت کے بعدان کی جگہ ناظم اعلی منتخب ہوئے اورپھرمسلسل تین برس تک اس منصب پرفائزرہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعدجماعت اسلامی سے وابستہ ہوگئے۔1977ء میں پاکستان قومی اتحاد کے ٹکٹ پرجھنگ سے الیکشن لڑا۔فیصل آباد اورلاہورجماعت کے سیکریٹری جنرل اورکوئٹہ جماعت کے امیرکے علاوہ1981ء میں کچھ عرصہ کے لیے مرکزی اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ 1989ء سے 1995ء تک امریکا میں رہے، جہاں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکا کی مجلس شوری کے رکن مقررکیے گئے۔
زندگی کاآخری دوراپنے آبائی ضلع جھنگ میں گزارا، جہاں مقامی امارت بھی کی اوروکالت بھی کی اورغالباًاپناکوئی اسکول وغیرہ بھی چلارہے تھے۔ ظفرجمال بلوچ کی زندگی کااہم ترین دورمگروہی ہے، جب بطور اسٹوڈنٹ لیڈرانھوںنے بھٹودورمیں دواہم تحریکوں ’بنگلہ دیش نامنظور‘ اور’ختم نبوت‘ میں طلبہ کی قیادت کی اوراس دوران میں قیدوبندکی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ ظفر جمال بلوچ کس مزاج کے اسٹوڈنٹ لیڈراور انسان تھے، اس کااندازہ اس دورمیںبھٹو صاحب کے ساتھ ہونے والی ان کی ملاقات کی روداد سن کر بھی ہوتاہے۔
کہتے ہیں کہ بھٹوصاحب نے مصطفیٰ کھرگورنرپنجاب کے ذریعے جمعیت کے جن تین عہدیداروںکوملاقات کی دعوت دی تھی،ان میں پنجاب یونیورسٹی یونین کے صدر جاویدہاشمی، انجینئرنگ یونیورسٹی یونین کے صدراحمدبلال محبوب کے علاوہ ظفرجمال بلوچ بھی شامل تھے، جو پنجاب یونٹ کے ناظم تھا۔ ان دنوں جمعیت دفترمیں ابھی ٹیلی فون بھی نہیں لگاتھا، لہٰذاگورنرکے سیکریٹری نے قریبی تارگھرفون کرکے ظفرجمال بلوچ کو بلایا اورکہا کہ بھٹوصاحب نے آپ تینوں کوملاقات کے لیے مری بلایاہے اوریہ حکم بھی دیاہے کہ میں اس کے لیے ہوائی جہازکے ٹکٹ بھی آپ کو پہنچا دوں۔
ظفرجمال بلوچ نے کہاکہ آپ نے جن تین طلبہ کے نام لیے ہیں، ان میں ہمارے ناظم اعلی تسنیم عالم منظرکانام نہیں ہے۔ ان کے بغیرہمارے آنے کاکوئی سوال نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہی آئیں گے اورآپ کے ٹکٹ پرنہیں، بلکہ اپنے خرچہ پرآئیں گے۔چنانچہ گزشتہ روز اپنے ناظم اعلیٰ کی قیادت میں ہی ظفرجمال، جاویدہاشمی اوراحمد بلال محبوب مری پہنچے، بھٹوصاحب شملہ مذاکرات پرجانے سے پہلے ہرشعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افرادسے ملاقاتیں کررہے تھے۔ یہ اطلاع ملنے پرکہ جمیعت کا وفد پہنچ گیا ہے، اندرسے بھٹوصاحب کا سیکریٹری برآمد ہوا اور کہا کہ بھٹو صاحب آپ کواندربلارہے ہیں۔
ظفرجمال بلوچ نے پوچھاکہ کیا بھٹوصاحب اکیلے ہی بیٹھے ہیںیاان کے پاس کچھ اورلوگ بھی ہیں۔ سیکریٹری نے کہا، پی ایس ایف کے کچھ لڑکے بیٹھے ہیںاور وہ بھی آپ سے ملیں گے۔ ظفرجمال بلوچ نے کہا، جب تک وہ پی ایس ایف کے لڑکوں کو باہرنہیں نکالیں گے، ہم ملاقات کے لیے اندرنہیں جائیں گے۔ کیونکہ ان کی موجودگی میں ملنا ان لاکھوں طلبہ کی توہین ہوگی، جنھوں نے ان کومستردکرکے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ سیکریٹری نے کہا، بھائی میں یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پھرسیکریٹری کے مشورہ پر ہی جاویدہاشمی نے اندرجاکر بھٹو صاحب سے یہ بات کہی۔ تھوڑی دیرمیں پی ایس ایف کے کارکن منہ لٹکائے باہرآرہے تھے۔
بھٹوصاحب نے پیغام بھیجا کہ میںنے ان کوفارغ کردیاہے، اب آپ لوگ اندرآجائیں۔اندرکی ملاقات کی کہانی ظفرجمال بلوچ اس طرح سناتے تھے، بھٹو صاحب نے کہا، دیکھومیں طلبہ ہی کی وجہ سے اقتدارمیںآیا ہوں، مگردکھ اس بات کاہے کہ جب میرے پاس تمھیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس وقت تم نے مجھ سے تعاون کیااوراب جب میں تمھیں کچھ دے سکتا ہوں توتم میری مخالفت کررہے ہیں۔ اورپھرتم لوگ مجھ سے کس لیے ناراض ہو؛کیاسردارشوکت حیات کے لیے، جس کومیں نے سینما کا پرمٹ دے دیاہے اوراب اس کو مجھ سے بڑھ کر اسلام جمہوریت اورملک کاکوئی خیرخواہ نظر نہیں آتا۔ یا ممتاز دولتانہ کے لیے، جس کومیں نے سفیر مقرر کیا ہے، اور اس کواب مجھ میں ہرطرح کی خوبیاں نظر آنے لگی ہیں یا خان قیوم خان کے لیے جس کو میں نے وزیرداخلہ بنادیاہے اوراب وہ دن رات میری تعریفیں کرتا رہتا ہے۔
کیا تم ان کرپٹ لوگوں کے لیے مجھ سے لڑتے ہو۔ غالباًتسنیم عالم منظرنے کہاکہ جناب، ہمارے لیڈرمولانامودودی ہیں،اگرانھوں نے بھی آپ سے کچھ مانگاہے توبتادیں۔اس پربھٹو صاحب خاموش ہوگئے اورکہا، میں ان کی بات نہیں کررہاتھا۔بھٹو صاحب کی عادت تھی کہ جو بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا، وہ اس کی سنتے کم اوراپنی سناتے زیادہ تھے۔ ہم نے یہ حکمت عملی اختیارکی کہ جہاں وہ سانس لینے کے لیے رکتے، ہم باری باری بولناشروع کردیتے۔ میں نے اپنی باری پرکہا، بھٹوصاحب، یہ جوآپ نے جلسوں میں ہاتھ کھڑے کرواکرعوامی فیصلے سنانے کا سلسلہ شروع کررکھا ہے، مہربانی فرماکراس کوختم کردیں،کل کویہ آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔
انھوں نے سوال کیا، کیسے۔ میں نے کہا، ابھی پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی میں الیکشن ہوئے، افتخارتاری اور مصطفے کھرکی مداخلت کی کوشش پر طالب علم مشتعل ہوگئے۔جلوس نکلااورنعرے لگاتا ہوا پنجاب اسمبلی کے باہرپہنچ گیا، جہاںانھوں نے ہاتھ کھڑے کیے اورنعرے لگائے کہ تاری اورکھرکوپھانسی دو۔ وہ لوگ جو آج ہاتھ کھڑے کرکے تاری اورکھرکی پھانسی کامطالبہ کر رہے ہیں، کل وہ ہاتھ کھڑے کرکے اس سے آگے کابھی کوئی مطالبہ کرسکتے ہیں۔
جیسے ہی میں نے بات مکمل کی، بھٹو صاحب نے کہا، نہیں اب میں ہاتھ کھڑے نہیں کراؤں گا، میں ہاتھ کھڑے نہیں کراؤں گا، میں اسمبلی میںبات کروں گا۔ ملاقات کے بعدجب ہم اٹھنے لگے توبھٹوصاحب نے ایک ہاتھ اپنی پتلون کی جیب میں رکھااوردوسرا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا۔ جواباًہم میں سے بھی جس جس نے پتلون پہن رکھی تھی،اس نے بھی شعوری طور پرایک ہاتھ پتلون کی جیب میں رکھااوردوسرامصافحے کے لیے آگے بڑھایا۔ میں نے شلوارقمیص پہن رکھی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ کمر پر رکھ لیا اور دوسرا بڑھا دیا۔ ہم باہرآئے توان کاملٹری سیکریٹری جودروازے پرکھڑایہ منظردیکھ رہاتھا، کہنے لگا، آپ کو معلوم نہیں آپ ملک کے صدر سے مل رہے ہیں۔
میں نے کہاکہ انھیں معلوم نہیں تھاکہ وہ ملک کی منتخب طلبہ قیادت سے مل رہے ہیں۔ظفرجمال بلوچ کے ساتھ مسئلہ مگریہی ہواکہ بعد کو زندگی بھر کے لیے وہ اپنے اس طالب علمی کے دور کے اسیر ہو کر رہ گئے، جس کی وجہ سے جہاں عملی زندگی میں ان کے لیے کئی مسائل پیداہوئے، وہاں جماعت بھی ان کی صلاحیت کار سے خاطرخواہ فائدہ نہ اٹھاسکی۔ وہ جہاں بھی رہے اورجہاں بھی گئے، بے چین، بے کل اورمضطرب ہی رہے ؛ بہرحال اب وہ اپنے رب کے حضورپہنچ گئے ہیں، جہاں قرارہی قرارہے۔
-

بڑے لوگوں کا اقبالؒ
کیا یہ ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی نہیں کہ ہم اقبالؒ جیسی شخصیت کے وارث ہیں؟ ہم دنیا کے سامنے یہ فخریہ کہتے ہیں کہ ہمارے اقبالؒ نے دنیا کو نئی راہیں دکھائی ہیں۔ انہوں نے ملی و ادبی خدمات کو وظیفۂ حیات مانتے ہوئے مدح و ذم سے بے نیاز ہو کر انجام دیا۔ وہ تعریف کے ڈونگروں، مرحبا کے ترانوں، زندہ باد کی صدائوں اور خوشامدی حربوں سے نہ واقف تھے نہ خواہاں۔ اسی لیے اس سب کچھ کے علی الرغم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کی ملی خدمات، ادبی کمالات اور دردمندی کو ان کی زندگی سے لے کر اب تک جو خراجِ تحسین پیش کیا جا رہا ہے، وہ شاید کم کم کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اقبالؒ کے حوالے سے جب جب کچھ پڑھنے کو ملتا ہے تو مایوسیوں میں اُمید کی شمع روشن ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اقبالؒ خیال و عمل کو نئی راہوں سے روشناس کراتا ہے۔ آئیے، اپنے محدود مطالعے کی مجبوری کو تسلیم کرتے ہوئے، ذرا دیکھتے ہیں کہ اقبالؒ کی صدا اور ان کے فکروعمل کو اس عہد کے بڑے بڑے لوگوں نے کس طرح محسوس کیا ہے۔
: قائداعظم محمد علی جناحؒ
٭ بھارت کے دستوری مسائل کے محتاط مطالعے اور تجربے کے دوران ان (اقبال) کے خیالات نے بالآخر مجھے انہی نتائج پر پہنچا دیا جن پر اقبال خود پہنچے تھے۔
٭ مجھے اس امر کا فخر حاصل ہے کہ ان (اقبال) کی قیادت میں مجھے ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار رفیق اور اسلام کا شیدائی نہیں دیکھا۔٭ ۱۹۲۹ء سے میرے اور سرمحمداقبال کے نظریات میں ہم آہنگی ہوئی اور وہی ایک عظیم اور اہم مسلمان تھے جنھوں نے ہر مرحلے پر میری حوصلہ افزائی کی اور آخری دم تک میرے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہے۔
: سید نذیر نیازی
٭ اقبال کی فکر بھی ایک طرح کا عمل ہے اور اگر عمل کے معنی ہیں نصب العین کے لیے ترغیبات تو حضرت علامہ کسی صاحبِ عمل سے پیچھے نہیں تھے۔
٭ محفل میں حضرتِ اقبالؒ کی گفتگو معمولی سے معمولی مسائل، واقعات اور حوادث سے پھیلتے پھیلتے اسلام، عالمِ اسلام، تاریخ، تمدن، سیاست اور معیشت سب پر چھا جاتی۔ انسان، کائنات، عمل و عقل، فکرووجدان، ادب اور فن سب اس کی زد میں ہوتے۔ اس پر حضرت علامہ کا حُسنِ بیان، صاف و سادہ اور دل نشین الفاظ، فصاحت و بلاغت، برجستگی اور بے ساختگی، توجہ اور التفات، شفقت اور تواضع، خلوص اور دردمندی، کہ جو ارشاد ہے، دل میں اُتر رہا ہے، ہر بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے۔ پھر اُن کا انکسارِعلم، شگفتگی اور زندہ دلی کہ نہ غرور، نہ تمکنت، متانت بھی ہے تو ظرافت کی چاشنی سے خالی نہیں۔ حقائق و معارف کی دنیا سامنے ہے۔ قلب و نظر کے حجاب اُٹھ رہے ہیں۔ دل و دماغ کا رنگ نکھر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا بے تصنع گفتگوئیں اور کیا بے تکلف صحبتیں تھیں۔٭ گفتگو کرتے ہوئے حضرت اقبالؒ کی ہر بات دل میں اُتر جاتی تاآنکہ وہ اپنے مخاطبین سے اتنے قریب ہوجاتے کہ انھیں گمان ہوتا حضرت علامہ شاید انہی کی طرح سوچتے ہیں، حتیٰ کہ اُن کے مسائل بھی انہی کے مسائل ہیں۔ وہ دیکھتے کہ بایں ہمہ علم و فضل اور بایں ہمہ دانش و حکمت، اُن کے اور حضرت علامہ کے درمیان کوئی دُوری ہے نہ حجاب۔ یوں حضرتِ علامہ کا حُسنِ التفات، اُن کا خلوص اور دردمندی، تواضع اور انکسار انھیں اُس دنیا میں لے آتا جو گردشِ لیل و نہار سے آزاد، ثبات و دوام کی دنیا ہے، جہاں جلال و جمال، خیروصداقت سے ہم کنار ہیں اور جس میں حضرت علامہ کا ایمان و یقین، ان کا ذوق و وجدان اور فکرونظر جب اُن کی راہنمائی کرتا تو وہ اپنے اندر نہ صرف عظمتِ ذات کی جھلک دیکھتے، بلکہ محسوس کرتے کہ انھوں نے ایک کہیں زیادہ حقیقی، کہیں زیادہ لطیف، کہیں زیادہ برتر اور پاکیزہ تر دنیا میں قدم رکھا ہے۔
: سید سلیمان ندوی
٭ دنیا سے اُٹھ جانے کے باوجود راہنمائی اقبال سے طلب کی جائے گی۔
سید عطاء اللہ شاہ بخاری
٭ اقبال، جدید دانش اور قدیم حکمت کا نقطۂ معراج۔ چونکہ میاں (حضورِاکرمؐ) سے محبت رکھتے تھے، اس لیے اللہ نے ان پر علم و دانش اور فکرونظر کی راہیں کھول دیں۔: شیخ عبدالقادر
٭ جُوں جُوں اُن کا مطالعہ، علم و فلسفہ کے متعلق گہرا ہوتا گیا اور دقیق خیالات کے اظہار کو جی چاہا تو انھوں نے دیکھا کہ فارسی کے مقابلے میں اُردُو کا سرمایہ بہت کم ہے اور فارسی میں کئی فقرے اور جملے سانچے میں ڈھلے ہوئے ایسے ملتے ہیں کہ جن کے مطابق اُردُو میں فقرے ڈھالنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے وہ فارسی کی طرف راغب ہوگئے۔: مولانا غلام رسول مہر
٭ اقبال انسانیت کے اعلیٰ مقاصد کے مُعلم، اسلامی حقائق کا شارح اور اسلام کی آفاقیت کا بہت بڑا داعی ہے۔ وہ ان برگزیدہ اصحاب، فکرونظر میں شامل ہے جن سے قدرت صدیوںبعد عالمِ انسانیت کو شرف بخشتی ہے۔: خواجہ حسن نظامی
٭ جسم پنجابی، دماغ فلسفی، خیال صوفی، دل مسلمان۔” عبدالمجید سالک
٭ اقبال نے اُردُو شاعری کو مریضانہ زارنالوں، حسرت و حرماں اور مایوسی و افتادگی سے نجات دلا کر حیات افروز اور جذبہ انگیز خیالات نظم کرنے پر مجبور کیا۔: ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری
٭ غمِ دوراں کا ایسا نوحہ خواں اور عظمتِ انسان کا ایسا قصیدہ خواں بیسویں صدی میں کوئی شاعر نہیں ہوا۔: ڈاکٹر جاوید اقبال
٭ اقبال کی رُوح کی بے تابی، بے چینی اور بے قراری آج بھی اقبال کے رازدانوں کے سینوں میںشعلہ کی طرح لپکتی ہے۔
٭ اقبال کی نکتہ آفرینی کے طلسم نے افکار کی گوناںگونی سے وحدتِ ایمانی پیدا کی ہے اور ایک ایسی منطق کو، جو محض مدرسوں کے طلبہ تک محدود تھی، ایک عالمگیر پیغام کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھ دیا۔
٭ اقبال مظاہرِ الٰہی میں سے تھے۔ ایسے نابغۂ روزگار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدیے کے طور پر ہی انسانوں میں نمودار ہوتے ہیں، آرڈر دے کر نہیں بنوائے جاسکتے۔
٭ اقبال گھر پر ہوتے تو اُن کے ملاقاتیوں کا تانتا نہیں تھمتاتھا۔ ناشتا، دوپہر کا کھانا، شام اور رات کی چائے طشتری میں لگ کر اُن کے کمرے میں جاتی تھی، لیکن لوگ تب بھی اُن کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔
٭ اقبال کا بیشتر وقت ایسے معاملات کی نذر ہوتا رہا جو انھیں اور ان کے خاندان کے باقی افراد کو باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنا سکیں۔ تحقیق و تصنیف کی خاطر فرصت کے لیے وہ تمام عمر ترستے رہے اور شعر شب بیداری کے عالم میں یا پھر تعطیل کے دنوں میں کہتے تھے۔ بعض اوقات مضامین سیلاب کی طرح اُمنڈ کر آتے اور الفاظ میں ڈھلے ہوئے اشعار کا طوفان بپا ہوجاتا، جیسے کسی مچھیرے کے جال میں بہت ساری مچھلیاں آ پھنسی ہوں اور وہ اس کشمکش میں ہو کہ کس کو پکڑے اور کس کوجانے دے۔: مریم جمیلہ
٭ اقبال کی’’ اسرارِخودی‘‘ کے انگریزی ترجمے کے باوجود میں نے اسے مسحورکن پایا۔ بہت سے شاعر، جو مختلف ثقافتوں اور زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اُن کی شاعری کا محور صرف قدرت کی خوبصورتی اور عاشقانہ محبت ہوتی ہے۔ اقبال وہ شاعر ہیں جس کی شاعری اسلام کی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ ایک معروف کہاوت ہے کہ آرٹ اور پروپیگنڈہ کبھی مل نہیں سکتے۔ لیکن اقبال جیسے ذہین شخص نے اس کہاوت کو غلط ثابت کردیا۔ اقبال ان بہت تھوڑے لوگوں میں شامل ہیں جن کی شاعری ناصحانہ ہونے کے باوجود خوبصورتی نہیں کھوتی۔: قدرت اللہ شہاب
٭ اقبال کی شخصیت دراصل ایک کثیر العباد (Multidimentional) شخصیت تھی۔ عالمِ اسلام میں وہ اپنی سطح کے پہلے شاعر اور فلسفی تھے جنہیں مشرق و مغرب کے علوم و فنون، فکروفلسفہ، تاریخ و تمدن کے روایتی اور جدید پہلوئوں پر صرف مطالعہ کے طور پر ہی نہیں بلکہ عملی مشاہدہ کے طور پر بھی بڑا عبور حاصل تھا۔ اتنے بڑے سمندر میں خیال اور بیان کی لہریں کسی خاص منتظم ترتیب کے ساتھ نہیں اُبھر سکتیں۔ یہ لہریں آڑی ترچھی بھی ہوں گی، متقاطع، متحارب ور معارض بھی۔ علامہ کا کمال یہ ہے کہ بھنوروں اور گردابوں کے ان ریلوں میں بھی اُن کے فکری بہائو کے ۲؍ واضح اور متوازن رُخ برقرار ہیں ۔ مادی دنیا کے معاملات میں وہ بڑی حد تک عملیت پسند (Pragmatic) ہیں۔ یہاں پر ان کی فکر کا رجحان اور اسلوب اپنے مطالب کو بطور نفس الامر بیان کرتا ہے اور یہ نفس الامر یا امرِواقعہ کبھی حتمی نہیں ہوتا بلکہ وقت، ماحول اور دیگر عوامل کے ساتھ ادلتا بدلتا بھی رہتا ہے۔ لیکن جہاں تک داخلی یا روحانی یا اسلامی افکاروبیان کا تعلق ہے، اقبال کی شاعری اور نثر دونوں یکساں طور پر مستقیم، مسلسل اور یک رنگ ہیں۔: این میری شمل
٭ مذہب کی تاریخ میں جسے ’’پیغمبرانہ‘‘ انداز کا تجربہ کہا جاتا ہے، اقبال اُس کی بہترین مثال تھے۔: فقیرسیدوحیدالدین
٭ اقبال کی شخصیت بہت عظیم المرتبت تھی۔ لیکن اُن کی ذاتی زندگی مردِ درویش و قلندر کے مانند تھی۔ سیدھی سادھی معاشرت، کوئی تصنع نہیں، کسی قسم کا کّرِوفر نہیں۔ مکان کے درودیوار آرایش سے عاری۔ ہر شخص ان تک بغیر کسی دشواری کے پہنچ سکتا تھا۔ آرایش اور نمائش کی طرف اُن کی نظر ہی نہیں جاتی تھی۔ ان کی زندگی ایک صابر اور متوکل مسلمان کی زندگی اور اُن کا عمل ان کے فکرونظر کا نمونہ تھا۔: ڈاکٹر فرمان فتح پوری
٭ اقبال کو اس بات سے چڑ تھی کہ شاعری یا کوئی اور فن افادیت و مقصدیت اور زندگی کی تعمیروتہذیب سے عاری ہو۔: ڈاکٹر بصیرہ عنبرین
٭ علامہ اقبال کے ہاں فکرِعمیق کی پیش کش، اُردُو اور فارسی دونوں زبانوں میں نہایت پُرتاثیر اسلوب میں ہوتی ہے۔ خاص طور پر فارسی زبان میں علامہ اقبال نے غیرمعمولی ذہانت و فطانت کا اظہار کیا ہے۔: فیض احمد فیض
٭ جہاں تک شاعری میں حساسیت، زبان پر عبور اورغنائیت کا تعلق ہے، ہم تو اُن (اقبال) کے خاکِ پا بھی نہیں۔ اگر علامہ سوشلزم کے معاملے میں ذرا سنجیدہ ہوجاتے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔: شورش کاشمیری
٭ لوگ جُوں جُوں کلامِ اقبال سمجھتے جائیں گے، ان میں فراتِ زیست سے مردانہ وار گزرنے کا حوصلہ اور صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔
٭ اقبال کو پاکستان سے محذوف کر دیں تو پاکستان ذہانتِ ملی کے اعتبار سے محض ایک بیان رہ جاتا ہے۔
٭ اقبال نے روانی و جولانی، ظرافت و سلامت، تجربہ و تمثیل، آواز و طریق، استدلال و اشارات اور تخلیق و فن کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ مجھے اُن کے ساحر ہونے کا یقین ہوگیا۔
٭ اقبال نے بلاشبہ کروڑوں انسانوں کو بالواسطہ اور بلاواسطہ متاثر کیا اور شاید پوری تاریخِ انسانی میں اس لحاظ سے اتنا بڑا شاعر کوئی نہیں۔
عرفان صدیقی (انڈیا)
٭ اقبال کے ہاں تاریخی، مذہبی، اساطیری حوالے، تلمیحات اور استعارے بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے ہمیں لغت سے زیادہ انسائیکلوپیڈیا کی ضرور پڑتی ہے۔
٭ اقبال زبان کے بہت بڑے ماہر تھے۔ زبان سے ان کا بڑا اجتہادی رشتہ تھا بلکہ کہیں کہیں تو بڑا باغیانہ رشتہ ہوجاتا ہے۔
٭ عشق کو آپ پرانے حوالے سے پڑھنا چاہیں گے تو اقبال آپ پر کھلیں گے ہی نہیں۔ اقبال نے بہت سے شعری کلیدی الفاظ استعمال کیے لیکن ان میں دوسرا رنگ اور معنویت بھر دی ہے۔ اس معنویت کی تلاش اقبال کی تفہیم میں ایک بڑا کام ہے۔: سید اقبال عظیم
٭ اقبال کو اُردُوشاعری کی معراج سمجھتا ہوں۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ تمام شعراء میں سے صرف ایک کا انتخاب کرو تو بلاتامل اقبال کا دامن تھام لوں گا، اس لیے کہ اقبال نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، وہ ہمارے پورے سرمایۂ شاعری پر بھاری ہے۔: شمس الرحمن فاروقی
٭ اقبال کے کلام کی ایک طرح سے بنیادی لے یا زیریں لہر یہی سوال ہے کہ کائنات میں انسان کا کردار کیا ہے اور کائنات سے انسان کا رشتہ کیا ہے؟ اس کی انہیں بہت فکر ہے اور وہ اس کے بارے میں بہت سوچتے ہیں اور بہت پوچھتے رہتے ہیں۔ خود سے بھی، اللہ سے بھی، تمام لوگوں سے بھی۔ خود کائنات سے سوال کرتے ہیں اور غالباً پہلی بار اتنا تجسس، اتنا سوال اور استفسار اُردُو کی شاعری میں نظر آتا ہے۔: ڈاکٹر عبدالغنی
٭ نظم’’ طلوعِ اسلام‘‘ میں اتنے پھیلے ہوئے مواد کو سمیٹ کر ایک منظم ہیئت مرتب کرنا اور شروع سے آخر تک بنیادی تخیل کو مسلسل ترقی دینا نہ صرف ایک غیرمعمولی ذہنی استعداد کا ثبوت ہے بلکہ زبردست جذبہ قلبی کا نشان ہے۔ اس میں فکر کی وسعت اور فن کی بلوغت اپنے عروج پر ہے۔ یقینا یہ ایک الہامی کیفیت کا سرچشمہ ہے۔: ڈاکٹر رشید امجد
٭ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے فرد کی انفرادیت کو نمایاں کرتے ہوئے اسے ایک ایسا ولولہ عطا کیا جس کے بل بوتے پر وہ سامراج سے ٹکرانے کی ہمت پیدا کرسکتا تھا۔ انہوں نے ماضی کی قوت سے حال کا مقابلہ کرنے کی تدبیر کی۔: ڈاکٹر صفدر محمود
٭ علامہ سے محبت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے فلسفہ، تاریخ و حدیث، عربی، فارسی اور تاریخِ اسلام پر گہری نظر ضروری ہے۔: جاوید ہاشمی
٭ دیکھا تو یہی دیکھا کہ جو اقبال کے سحر میں گرفتار ہوجائے، اُسے اپنی منزل چرخِ نیلی فام سے پرے نظر آتی ہے۔: ہارون رشید
٭ اقبال ایک آدمی بھی نہیں، فقط ایک ادارہ بھی نہیں۔ اقبال ایک حیرت کدہ ہے، تاریخ میں جس کی کوئی دوسری نظیر نہیں۔ اس جہان میں جو داخل ہوا، عمر بھر اُسی کا ہورہا۔
٭ اُردُوشاعری کے ہاتھ میں بھیک مانگنے کا کشکول اور آواز میں خودترسی تھی، جب وہ (اقبال) شعر کے افق پر اُبھرے، اُمید، ایمان اور عزم کی مشعل تھامے، چالیس برس اُس نے اُردُوادب کے دھندلے میدانوں کو روشنی سے بھردیا۔ انسان کی پوری تاریخ میں کوئی شاعر ایسا نہ تھا جس نے سیاسی، لسانی اور فکری اعتبار سے کسی معاشرے کو اتنی گہرائی اور وُسعت میں متاثر کیا ہو۔ اُردُو زبان کے تیور ہی اُس نے بدل ڈالے، اُس کا نسائی لہجہ مردانہ ہوگیا۔: محمد حسین گوہر
٭ اقبال نے اُردُوشاعری کو فکر اورذوقِ یقین دیا۔ اقبال کی شاعری کی ہمہ گیری، حیات آفرینی، فعالیت و عملی امکانات، انقلابی حیات آفرینی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اُن کا فلسفۂ خودی فرد کو اپنی شخصیت کی تکمیل پر آمادہ کرتا ہے اور اُسے سماجی مقاصد سے ہم آہنگ انجمن آرائی کے کام میں لاتا ہے۔
٭ اقبال گزشتہ میں ثبت ایک نقش نہیں ہے، آیندہ کے لیے ایک امکان اور بشارت کا زندہ و جاوید نشان ہے۔
٭ عقل پر وجدان کو، بے روح عبادت پر مذہبی تجربے کو، روایت زدگی پر مہم جوئی کو اور تسلیم و رضا پر تسخیر کی طلب اور شوقِ فروزاں کو اقبال جو ترجیح دیتے ہیں تو اسی لیے کہ زندگی جیسی کہ ہمیں میسر آتی ہے، اُسے ارتقاپذیر اور متحرک اور کارکشا رکھنے کے لیے، اس کے امکانات کا سراغ لگانا، انہیں دریافت کرنا ضروری ہے۔ دانش اور بصیرت کی یہ لہر اقبال کی سرشت میں صرف روایتی تصورات کے توسط سے نمودار نہیں ہوئی۔ اقبال نے اس کی ترتیب و تشکیل کے عمل میں اپنی ذہنی روایت اور پس منظر کے علاوہ دوسری روایتوں اور سرچشموں سے بھی استفادہ کیا۔
٭ اقبال گردوپیش کی دنیا کے مظاہر اور اشیا میں ابتری اور باہمی لا تعلقی کے باوجود ایک تنظیم کے خواب سے کبھی دست بردار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی نظر انسانی صورت حال کی حقیقت کے ساتھ ساتھ اس کے امکان پر بھی تھی۔ وہ ایک مستحکم اور پائیدار مستقبل بین (Futuristic) رویہ رکھتے تھے۔: سیدابوالحسن علی ندوی
٭ زندگی کے طویل تر دور میں دماغ پر علامہ اقبال کا بڑا غلبہ رہا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ کسی معاصرشخصیت کے افکار کا اتنا گہرا اثر دماغ پر نہیں پڑا جتنا علامہ اقبال کے کلام کا۔
٭ اقبال کو میں نے اولوالعزمی اور ایمان کا نوحہ خواں شاعر پایا۔ جب بھی میں نے ان کا کلام پڑھا تو دل جوش سے اُمنڈ نے لگا اور لطیف جذبات نے انگڑائیاں لینا شروع کردیں۔ احساسات و کیفیات کی لہریں بیدار ہونے لگیں اور رگوں میں شجاعتِ اسلامی کی رُوح دوڑنے لگی۔
٭ اقبال کی آہِ سحرگاہی اس کا اصل سرچشمہ ہے۔ جب سارا عالم خوابِ غفلت میں پڑا سوتا رہا، اس اخیرِشب میں اقبال کا اُٹھنا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوجانا، پھر گڑگڑانا اور رونا، یہی چیز تھی جو اس کی روح کو ایک نئی نشاط، قلب کو نئی روشنی اور ذہن کو فکری غذا عطا کرتی ہے۔
٭ اقبال کی فنی مہارت و چابکدستی اور بلیغ منظرکشی و سماں بندی کہ حالات و واقعات کی تصویر نگاہوں میں پھر جائے اور قال حال اور جنت نظیر بن جائے۔
٭ اقبال اپنی تدریسی، دقیقہ سنجی، دروں بینی اور بالغ نظری سے ملکوں، تہذیبوں، مذہبوں اور قوموں کی روح میںاُترجاتے ہیں اور پھر اپنا ذاتی مشاہدہ اور صداقت کا تجربہ و تجزیہ شعرونغمہ کے پردوں کی آڑ میں ہوبہو سامنے رکھ دیتے ہیں۔: نعیم صدیقی
٭ وہ قوت جسے مذہب قرار دے کر شعروفن کی محفلوں سے نکال دیا گیاتھا اُسے اقبال ایک پُرعظمت تحریک کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے کرایوانِ سخن میں داخل ہوئے۔
٭ اقبال نے دلوں اور دماغوں پر نہایت ہی گہرا اثر اس لیے ڈالا کہ ملت نے اپنے سفرِجستجو میں اُس کے شعلۂ نوا کو بہترین قندیل پایا ہے۔ ان کے یہاں ہمیں اپنی بکھری ہوئی ہستی کا سراغ ملتا ہے۔ ہم کیا تھے؟ کیا ہوگئے؟ اور ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ کون سے عقائدوتصورات ہمارے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمارا ڈھانچہ کن اصولوں، قدروں اور روایتوں سے بنتا ہے؟ ہماری زندگیوں کا اعلیٰ ترین مشن کیا ہے؟ ہمارے انسانِ مطلوب کے خدوخال کیا ہیں؟ ان سوالوں کا اقبال کے یہاں واضح جواب ملتا ہے یا کم از کم جواب تک پہنچنے کے لیے واضح اشارے ملتے ہیں۔
٭ اقبال نے اسلام کی روشن صداقتوں کو شعر میں اس شان سے سمویا کہ شعریت کو کوئی ضعف نہیں پہنچا بلکہ شعریت اور زبان نکھر گئی۔ فن کے ناوک اور زیادہ نوکیلے ہو کر دلوں میں ترازو ہوگئے۔: رشید احمد صدیقی
٭ معلوم ہوتا ہے جیسے شاعری نے اقبال کو اقبال بنانے میںاپنی ساری آزمائشیں ختم کر دی ہوں اور اُن کے بعد ان پر ساری نعمتیں بھی تمام کر دی ہوں۔ جیسے اُردُوشاعری کا دین اقبال پر مکمل ہوگیا ہو۔ اس کے باوجود اقبال کی فکرونظر کی وسعت اور گہرائی کا یہ عالم ہے کہ اس کا بہت کم حصہ ان کے کلام میں منتقل ہوا ہے۔
حرفِ آخر، یقینا یہ اقبال کی فکروعمل کا کمال ہے کہ ہر کسی نے گلشنِ اقبال میں بکھرے رنگوں اور خوشبوئوں کو اپنے ہی انداز سے محسوس کیا اور یوں ہر کسی پر ایک نئی واردات و کیفیت منکشف ہوئی،حالانکہ اقبال تو یہی سمجھتے تھے کہ ؎
اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے
کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے: ڈاکٹر ندیم
کلامِ اقبال خیال و عمل کو نئی راہوں سے روشناس کرنے میں مددگار ہے۔: سید نذیر نیازی
علامہ کا انکسارعلم، شگفتگی اور زندہ دلی ایسی کہ نہ تعلیٰ، نہ غرور، نہ تمکنت صرف صاف و سادہ اور دل نشین الفاظ اُن کا بیان ہوتے۔: مولانا غلام رسول مہر
اقبال انسانیت کے اعلیٰ مقاصد کے مُعلم اور اسلام کی آفاقیت کے بہت بڑے داعی تھے۔: ڈاکٹر اختر رائے پوری
اقبال سے بڑا عظمتِ انسان کا قصیدہ خواں اور کوئی نہیں۔: ڈاکٹر جاوید اقبال
اقبال کی نکتہ آفرینی کے طلسم نے افکار کی گوناںگونی سے وحدت ایمانی پیدا کی۔ وہ مظاہرِ الٰہی میں سے تھے۔
بشکریہ اردو ڈائجسٹ -
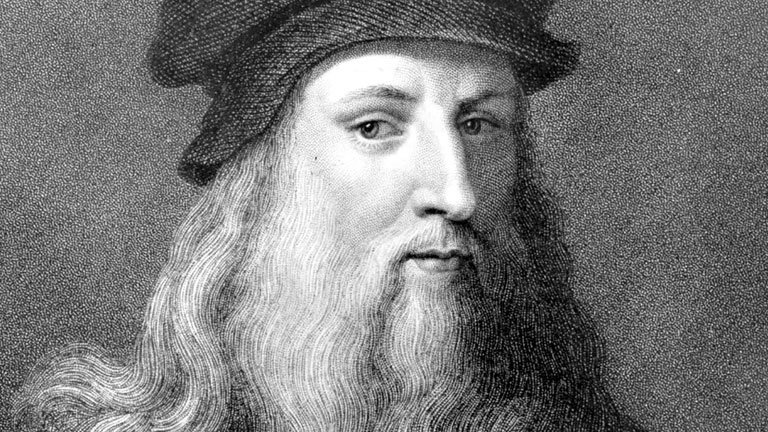
لیونارڈو ڈی ونچی، ایک ناقابل فراموش انسان – عمران ناصر
 انگلش کا محاورہ ”جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر آف نن“ جس کا مناسب ترین ترجمہ ”ہرفن مولا، ہرفن ادھورا“ ہوسکتا ہے۔ یعنی ہرکام کے بارے میں علم ہونا لیکن ظاہر ہے علم ایک سمندر ہے اورعلم کی کسی ایک شاخ پر ہی پوری زندگی بیت جائے تو علم کی تکمیل تو درکنار تکمیل کے قریب بھی پہنچنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ لیکن اس تصور کو اٹلی کے لیونارڈو ڈی ونچی اپنی عملاً مافوق الفطرت شخصیت سے باطل کر دیتے ہیں۔ لیونارڈو ڈی ونچی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں اوج ثریا کو چھوتے نظر نہیں آتے۔
انگلش کا محاورہ ”جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر آف نن“ جس کا مناسب ترین ترجمہ ”ہرفن مولا، ہرفن ادھورا“ ہوسکتا ہے۔ یعنی ہرکام کے بارے میں علم ہونا لیکن ظاہر ہے علم ایک سمندر ہے اورعلم کی کسی ایک شاخ پر ہی پوری زندگی بیت جائے تو علم کی تکمیل تو درکنار تکمیل کے قریب بھی پہنچنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ لیکن اس تصور کو اٹلی کے لیونارڈو ڈی ونچی اپنی عملاً مافوق الفطرت شخصیت سے باطل کر دیتے ہیں۔ لیونارڈو ڈی ونچی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں اوج ثریا کو چھوتے نظر نہیں آتے۔کہاجاتا ہے کہ اوسط درجے کا انسان اپنی دماغی صلاحیتوں کا محض 2 سے 3 فیصد استعمال کرتا ہے، باقی دماغ محض ایک جیلی کی طرح اپنے خول میں ہلکورے کھاتا بالاخر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سوال دماغ میں ابھرتا ہے کہ اگر بیدار مغز انسان سوفیصدی اپنے دماغ کواستعمال کرنا شروع کردے تو دنیا کیا رخ اختیار کرے گی۔ یقیناً یہ دنیا اپنی سائنسی ترقی کی ان منازل کو طے کرلے گی جو اسے طلسمات کے عجائبات میں لے جائے گی۔ شائد ”کن فیکون“ سے مشابہ معجزات وقوع پذیر ہونا شروع ہوجائیں۔
میراگمان ہے کہ لیونارڈوڈی ونچی ان انسانوں میں سے تھے جو نامساعد حالات میں رہتے ہوئے بھی سائنس کی ترقی کی راہ متعین کرگئے تھے۔ ابتدائی دور میں جب سائنس عہد طفولیت میں تھی۔ مستقبل کے احوال پردہ راز میں تھے، لیونارڈو اپنی جولانیوں اور مہم جویانہ طبعیت کے باعث آنے والے محیرالعقول سائنسی دور کو منکشف کرگئے۔ انہوں نے جہاز، ہیلی کاپٹر، بلٹ پروف گاڑیوں کا تصور دیا اور ان کے ابتدائی خدوخال واضح کیے. بحیثیت آرٹسٹ انہوں نے شہرہ آفاق مونالیزا اور دی لاسٹ سپر پینٹنگز کو تخلیق کیا۔ دنیا جدید بھی لیونارڈو کی تخلیق مونا لیزا کے سحرسے آزاد ہونے میں ناکام ہے۔
لیونارڈو ڈی ونچی کو کس نام سے یاد کیا جائے، یقیناً مشکل ترین کام ہگا کیونکہ ان کی وجہ شہرت کسی مخصوص میدان سے وابسطہ نہیں کی جاسکتی۔ انھوں نے مصوری، مجسمہ سازی، انجنیئرنگ، نقشہ نویسی اور ایجادات میں نام کمایا۔
لیونارڈو 15 اپریل، 1452 میں اٹلی کے ایک گاؤں ونچی میں پیدا ہوئے۔ اہل علاقہ میں لیونارڈو کے نام سے ہی پہچان پائی۔ لیونارڈو ایک غیرمنکوحہ جوڑے کے ہاں پیداہوئے۔ روایت کے مطابق لیونارڈو شاید والدین کی عدم توجہ کے باعث مدرسہ سے تعلیم نہ حاصل کرسکے، واجبی سی تعلیم گھر سے ہی حاصل کی۔ فن مصوری سے لگاؤ بچپن سے ہی تھا۔ مصوری کا فن ان کی ابتدائی تصاویرسے عیاں تھا جوقابل ستائش تھا۔ یہی ذوق مجسمہ سازی میں بھی ان کی پہچان کا باعث بنا۔ 14 سال کی عمر میں لیونارڈو میٹل ورک، لیدر ورک، وُڈ ورک، مجسمہ سازی میں نمایاں مہارت حاصل کرچکے تھے۔ علاوہ ازیں ان کی ڈائری سے یہ بھی منکشف ہوتا ہے کہ لیونارڈو جیولوجی اور اناٹومی پر بھی قابل رشک دسترس رکھتے تھے، اور ان کے مشاہدات اور تجربات ان علوم کے ابتدائی تصورات میں اہمیت خاص رکھتے ہیں۔
لیونارڈو کی زندگی نامساعد حالات اور نشیب وفرازسے عبارت ہے۔ انسان کی کامیابیاں بےشمار رکاوٹوں کو عبورکرنے کے بعد جنم لیتی ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف لیونارڈو کی زندگی سے بخوبی ہوتا ہے۔ لیونارڈو کا بچپن تلخ گھریلو زندگی میں گزرا۔ ناکامیوں سے دل گرفتہ ہونے کے بجائے لیونارڈو نے عزم واستقلال کی بےمثل تاریخ رقم کی۔ فرانس کے حملہ کے دوران لیونارڈو کو مسلسل ہجرت کا سامنا رہا۔ لیکن سعی پیہم نے بندہ خاک سے ناقابل فراموش کارنامہ ہائے انجام دلوائے۔ آرٹ کے میدانوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد لیونارڈو کے من میں تجسس کی ایک کونپل پھوٹی اور درجہ کمال رکھنے والی صلاحیتوں کا رخ جیولوجی اور اناٹومی کی طرف ہوا۔ یہاں سے لگن اور دوآتشہ جستجو نے اس مرد آہن کو شب و روز کی محنت پر مجبورکر دیا اور یوں، بائیسکل، پیراشوٹ، جہاز، ہیلی کاپٹر اور بلٹ پروف گاڑیوں جیسی معروف ایجادات کا سہرا لیونارڈو کے سر سجا۔
2 مئی، 1519ء میں 67 سال کی عمرمیں لیونارڈو نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ لیونارڈو کی زندگی ایک عزم و استقلال کی داستان ہے جس سے انسانیت کی خدمت کا انمول سبق ملتا ہے۔ لیونارڈو کے بارے میں ہی شاید غالب نے کہا تھا،
دام ہر موج میں ہے حلقہ صدکام نہنگ
دیکھیں کیا گزرے ہے قطرہ پہ گہرہونے تک -

جون ایلیا کی یاد – ہمایوں مجاہد تارڑ
 بھول گیا کہ آج مؤرخہ 8 نومبر تو لیفٹ ونگ سے میرے پسندیدہ ترین شاعر جون ایلیا کی برسی ہے۔وہی مجنوں قسم کا عجیب و غریب شخص: ”جون بہت عجیب ہوں میں، اتنا عجیب ہوں کہ بس – خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں“ کے خالق۔ ایک ایسا منفرد اور یگانہ شاعر جس کا انداز نہ پہلے گزرے کسی شاعر سےمیچ ہوا، نہ بعد میں کسی صاحب کو ان کے لب ولہجے بات کر تے دیکھا گیا۔ یوں، جون ایک عجیب و غریب شے تھے۔کسی نے درست کہا: “وہ اپنے سلسلہ کے آپ ہی موجد اور آپ ہی خاتم ہیں۔”
بھول گیا کہ آج مؤرخہ 8 نومبر تو لیفٹ ونگ سے میرے پسندیدہ ترین شاعر جون ایلیا کی برسی ہے۔وہی مجنوں قسم کا عجیب و غریب شخص: ”جون بہت عجیب ہوں میں، اتنا عجیب ہوں کہ بس – خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں“ کے خالق۔ ایک ایسا منفرد اور یگانہ شاعر جس کا انداز نہ پہلے گزرے کسی شاعر سےمیچ ہوا، نہ بعد میں کسی صاحب کو ان کے لب ولہجے بات کر تے دیکھا گیا۔ یوں، جون ایک عجیب و غریب شے تھے۔کسی نے درست کہا: “وہ اپنے سلسلہ کے آپ ہی موجد اور آپ ہی خاتم ہیں۔”
وہی جن کی ایک طویل نظم ‘اعلانِ رنگ’ مجھے زبانی یاد ہے، اور جن کا مجموعہ کلام”شاید” کبھی حرف بہ حرف پڑھا تھا۔فیس بک پر برادر صفتین خان کی ایک با کمال پوسٹ پر نظر پڑی تو دماغ جاگا۔ ویسے کیا خوبصورت جملہ کہا صفتین خان نے:
‘جون مرتا ہے تو اقبال جنم لیتا ہے۔’ بادی النظر میں یہ سٹیٹمنٹ محض 8 اور 9 نومبر کا اشارہ دیتی ہے۔اگرچہ ہے ذرا گہری بات کہ: کفر/انکار مرتا ہے، تب ایمان جنم لیتا ہے۔یا یوں کہ جون ایلیا مایوسی کی علامت ٹھہری ، جبکہ اقبال رجائیت و امّید کی۔
جون ایلیا کے نزدیک
‘ حاصل کُن ہے یہ جہانِ خراب – اتنی عجلت میں یہی ممکن تھا،’
تو اقبالؒ کے ہاں ‘سرّآدم ہے ضمیرِ کن فکاں ہے زندگی’ یا ‘قلزمِ ہستی سے تُو ابھرا ہے مانندِ حباب – اِس زیاں خانے میں تیرا امتحاں ہے زندگی’یا ‘فقط ذوقِ پرواز ہے زندگی’ ایسی سٹیٹمنٹس خون گرما دیتی ہیں۔
زندگی کی گہما گہمی میں رجائیت کا ساتھ ہو یابے جذبہ یاسیت کا، یہ ہر طرح گزر جاتی ہے، تاہم پُر امّید رہنے والے یہی وقت بہتر احساسات کیساتھ گزارتے ہیں۔اقبالؒ کے یہاں کائنات اور اس اندر موجودات و لوازمات خاص مقصدیت لیے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف جون ایلیا ایسے لوگ اور ان کی شاعری میں عدمِ مقصدیت پر اصرار ہی سب سے بڑی مقصدیت ہے۔
خیر، جون ایلیا بوجوہ دنیائے حرف و خیال میں ایک بڑا نام ہے۔بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایلیا کی شادی مشہور لیفٹسٹ کالمنسٹ زاہدہ حنا سے ہوئی تھی ، 1970 میں۔ کچھ عرصہ بعد علیحدگی ہو گئی تھی۔یہ بھی کم کم لوگ جانتے ہیں کہ جون ایلیا کی عربی اور فارسی زبانوں میں قابلیت کا یہ عالم تھا کہ مرحوم نے متعدّداہم کتابوں کے تراجم بھی کیے، اور اردو زبان میں متعدّد نئے الفاظ متعارف کرائے۔ سسپنس ڈائجسٹ میں ان کا انشائیہ کمال کی تحریر ہوا کرتی۔ان کے قارئین جانتے ہیں وہ ایک صاحبِ طرز ادیب تھے۔مجرمانہ حد تک اپنی شاعری کی نشر و اشاعت سے پہلو تہی کرنے والا یہ مردِ قلندر دنیائے اردو زباں میں اپنا نقش بڑی مضبوطی سے جما گیا ہے، جو انمٹ ہے۔
میری پسندیدہ نظم ‘اعلانِ رنگ’ میں سے چند لائنیں ذوقِ طبع کے لیے:
ہجوم گنجان ہو گیا تھا عمل کا اعلان ہو گیا تھا
تمام محرومیاں ہم آواز ہو گئی تھیں کہ ہم یہاں ہیں
ہمارے سینوں میں ہیں خراشیں ،ہمارے جسموں پہ دھجیاں ہیں
ہمیں مشینوںکا رزق ٹھہرا کے رزق چھینا گیا ہمارا
ہماری محنت پہ پلنے والو ہمارا حصہ تباہیاں ہیں!
مگر یہ اک خواب تھا، وہ اک خواب جس کی تعبیر خونچکاں تھی
رقم جو کی تھی قلم نے سرمایے کے وہ تحریر خونچکاں تھی
سفید پرچم نے خونِ محنت کو اپنے سینے پہ مل لیا تھا
یہ وقت کی سربلند تدبیر تھی یہ تدبیر خونچکاں تھی
دیارِ تاریخ کی فضائوں میں سرخ پرچم ابھر رہا تھا
یہ زندگی کی جلیل تنویر تھی یہ تنیر خونچکاں تھی
یکم مئی خون شدہ امنگوں کی حق طلب برہمی کا دن ہے
یکم مئی زندگی کے زخموں کی سرخرو شاعری کا دن ہے
یکم مئی اپنے خونِ ناحق کی سرخ پیغمبری کا دن ہے
یکم مئی زندگی کا اعلانِ رنگ ہے زندگی کا دن ہے
یہ زندگی خون کا سفر ہے اور ابتلا اس کی رہگزر ہے
جو خون اس سیلِ خون کی موجوں کو تند کر دے وہ نامور ہے
یہ خون ہے خون سر زندہ ، یہ خونِ زندہ ہے خونِ زندہ
وہ خون پرچم فراز ہوگا جو خونِ زندہ کا ہمسفر ہے
علی زریون نام کے شاعر نے جون ایلیا کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے:
کیا عجب ہے کہ وہ جو تھا ہی نہیں
لے کے “ہونے” کا معجزہ آیا
صاحب ِ کیفیت بہت ہیں ،مگر
لطف آیا تو جون کا آیا -
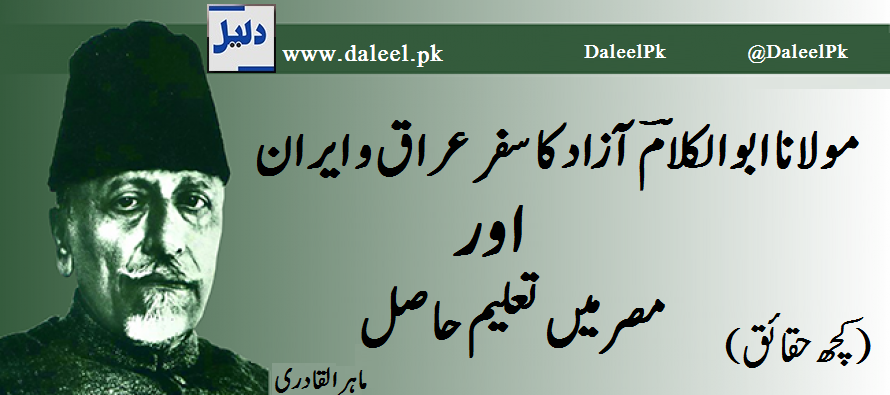
پردہ اٹھتا ہے! ماہر القادری
یہ مضمون بہت سوں کو حیرت میں ڈال دے گا،کسی کسی خوش فہم کو شاید پوری طرح یقین بھی نہ آئے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں اصلیت کتنی ہے اور “سخن طرازی” سے کس حد تک کام لیا گیا ہے! بہت سے لوگ سوچ میں ڈوب جائیں گے کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں،جن باتوں کا سان گمان بھی نہ تھا، وہ باتیں بے نقاب ہو کر سامنے آرہی ہیں،عجیب بلکہ عجیب تر انکشاف! مگر لوگوں کی حیرت واقعات کو تو نہیں بدل سکتی،کوئی سر سے پیر تک چاہے حیرت میں ڈوب ہی کیوں نہ جائے اس طرح غرقِ حیرت ہوجانے سے حقیقت اور واقعیت تو نہیں چھپ سکتی،اربابِ نظر کی خدمت میں میری مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ حیرت اور خوش فہمی،عقیدت اور حسنِ ظن سے اگر بالکل خالی الذہن نہیں ہوسکتے تو کم سے کم اس کے غلبہ اور شدت کو کم کر کے اس مضمون کا مطالعہ فرمائیں۔
مولانا ابوالکلامؔ آزاد کے سفرِ عراق و ایران اور مصر میں تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں کچھ باتوں کی بھنک جب راقم الحروف کے کان میں پڑی تو مجھے خود بہت تعجب ہوا،شروع شروع میں دل کو کسی طرح یقین ہی نہ آتا تھا کہ اتنا بڑا آدمی خود اپنے بارے میں اس قسم کی غلط بیانیوں سے کام لے سکتا ہے،دل بہت دن تک یہی تاویلیں کرتا رہا کہ بڑے آدمیوں کے بارے میں کچھ غلط اور بے سروپا باتیں بھی مشہور ہوجاتیں ہیں بلکہ مشہور کردی جاتی ہیں،کیا عجب ہے کہ یہ باتیں بھی اسی قبیل کی ہوں۔۔۔۔سب سے پہلے دہلی کے مشہور علمی ماہنامہ”برہان” میں مولوی مہر محمد خاں صاحب شہابؔ مالیرکوٹلوی کا ایک مضمون میری نظر سے گزرا،اس مضمون کے پڑھنے کے بعد خیال ہوا کہ ان باتوں کو اب تہمت و الحاق یا محض افواہ سمجھ کر نظرانداز نہیں کیا جاسکتا،معاملہ اب زبان و گوش تک ہی محدود نہیں رہا،بات خامہ و قرطاس تک آپہونچی ہے۔
مگر سنی سنائی باتوں پر جھٹ سے فیصلہ کر دینا بے احتیاطی ہی نہیں،بے دانشی اور ناانصافی بھی ہے،لہذا ابھی تک میں نے کوئی قطعی رائے قایم نہیں کی لیکن ہاں! یہ ضرور ہوا کہ شروع شروع میں جن باتوں نے مجھے غرقِ حیرت کردیا تھا اس حیرت میں کمی آگئی،یہ باتیں بہرحال تحقیق طلب تھیں اور میں نے جستجو شروع کر دی اسی عرصہ میں مشہور صحافی اور انشاپرداز جناب رئیس احمد جعفری کا ایک مقالہ “فاران” میں چھپنے کے لئے آیا،یہ مقالہ مولانا ابوالکلام آزادؔ کے سفرِ عراق و ایران کے متعلق تھا ،جس میں اس بات کو کنایوں،اشاروں اور استعاروں سے ہٹ کر، دو ٹوک انداز میں پیش کیا گیا کہ مولانا آزادؔ کے عراق و ایران کی سیاحت و سفر کا واقعہ ایک افسانہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا،میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس مضمون کو اپنے رسالے میں فوراً چھاپ دیتا کہ اس طرح کچھ نہ ہوگا تو کم سے کم لوگوں کو گرمئ محفل اور بحث و سخن کے لئے تو مسالہ مل جائے گا،مگر “فاران” کا ایک ایک صفحہ اس کا شاہد ہے کہ میں نے سستی شہرت کے لئے اس قسم کی بےاحتیاطیوں کا ارتکاب نہیں کیا،گرمئ محفل اور ہنگامہ آرائی میرے پروگرام میں شامل نہیں ہے،مسلمان اور پھر انکے ۔۔واہی تباہی باتیں منسوب کردینا بہت بڑا اخلاقی جرم ہے،”فاران” اس روشِ عام سے ہمیشہ بچ کر چلا ہے اور اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔
میں ابھی واقعات کی چھان بین ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں سہ روزہ “مدینہ”(بجنور) (مورخہ17اگست1951ء) کا ایک شمارہ نظر سے گزرا،جس میں اخبار مدینہ کے ایڈیٹر نے مولانا ابوالکلام آزادؔ سے مل کر بعض مسائل پر بالمشافہہ گفتگو کی تھی اور اس میں مولانا کے سفرِ عراق کا بھی ذکر آیا۔۔۔۔اب تک اس سلسلہ میں بہت سی باتیں میرے علم میں آچکی تھیں اور میں چاہتا تو ان معلومات اور اطلاعات کو منظرِ عام پر لے آتا مگر ضمیر نے اس کی اجازت نہ دی،دل نے کہا اور وجدان نے اس کی تائید کی کہ مولانا ابوالکلام آزادؔ جن سے ان واقعات کا تعلق ہے،خود ان سے استفسار اور تحقیق کرنا ضروری ہے،چوں کہ یہ ان کی ذات کا معاملہ ہے اس لئے صاحبِ ممدوح بہتر طریقہ پر روشنی ڈال سکیں گے،چنانچہ میں نے ایک نیازنامہ مولانا موصوف کی خدمت میں 31اگست1951ء کو رجسٹری کے ذریعہ روانہ کیا،جسے بلفظہ درجِ ذیل کیا جاتا ہے:بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
صاحب المجدد الکرم دامت معالیکم!
السلام علیکم و علیٰ من لدیکم!جناب والا سے چند ضروری باتیں دریافت طلب ہیں:
۱ ۔مکہ مکرمہ آپ کا مولد بتایا جاتا ہے مگر آپ کا منشاء کونسا مقام ہے؟
۲۔”الہلال” کے سرورق پر “المکنی بابی الکلام الدہلوی” چھپتا رہا ہے،”دہلی” کی مرزبوم سے آپ کی کیا نسبت اور کیا تعلق ہے؟
۳۔کیا “قصور(پنجاب) سے آپ کا کوئی خاندانی تعلق ہے؟
۴۔”غبارِ خاطر” میں آپ نے مصر،ایران،شام اور عراق کے سفر کا ذکر فرمایا ہے یہ سفر آپ نے کس سنہ اور کس ماہ یا مہینوں میں فرمایا تھا؟
۵۔(الف) مسٹر مہادیو ڈیسائی(آنجہانی) نے آپ کے حالاتِ زندگی لکھے ہیں،جن کا اردو ترجمہ مسٹر آصف علی نے کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ نے جامعہ ازہر میں تعلیم پائی تھی،براہِ کرم مطلع فرمایا جائے کہ آپ کس سنہ میں جامعہ ازہر کے طالبِ علم رہے ہیں؟
(ب) آپ کے زبانی حوالہ کی بنیاد پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کی شیوخ جامعہ ازہر سے علمی صحبتیں رہی ہیں،اس سلسلہ میں بھی سنہ کی ضرورت ہے۔
جناب والا کی گوناگوں مصروفیات کو دیکھتے ہوئے مختصر سے مختصر عریضہ لکھا گیا ہے تاکہ جناب کم سے کم وقت میں جواب عنایت فرما سکیں،ان پانچ سوالوں کے لئے زیادہ سے زیادہ پانچ سطروں کے لئے(بلکہ اس سے بھی کم) جناب کو زحمت کرنا ہوگی۔
یقین ہے کہ جواب سے ضرور مفخر فرمایا جائے گا!
نیاز کیش:ماہرؔ القادریدو ہفتہ سے کچھ زائد میں نے جواب کا انتظار کیا،جب اٹھارہ دن تک جواب نہ آیا تو میں نے یاددہانی کے لئے دوسرا عریضہ(پہلے رجسٹرڈ خط کا نمبر (193) اور دوسری رجسٹری کا نمبر (908) ہے!) مولانا ابوالکلام آزادؔ کی خدمت میں 18ستمبر 1951ء کو رجسٹری کے ذریعہ ہی بھیجا،جس کی یہ عبارت ہے:
گرامی منزلت دامت معالیکم!
ہدیہ سلام و رحمت!میں نے ایک رجسٹرڈ نیازنامہ 31اگست کو خدمتِ گرامی میں گزرانا تھا اس کے جواب کے لئے چشم براہ ہوں،براہِ کرم جواب جلد عنایت فرمایا جائے۔
والسلام
نیازمند:ماہرؔ القادریانقلابِ تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور ہندوستان دونوں حکومتوں میں ڈاک کا انتظام زیادہ اچھا نہیں رہا،اس لئے میں نے بہ نظرِ احتیاط مولانا آزادؔ کی خدمتِ گرامی میں دونوں خط رجسٹری کے ذریعہ حاضر کئے تھے کہ گم ہونے کا امکان باقی نہ رہے،میں بہت دنوں تک انتظار کرتا رہا کہ اب جواب آتا ہے،تب جواب آتا ہے مگر افسوس ہے کہ اس باب میں مجھے مایوس ہی ہونا پڑا،پہلے خط کو لکھے ہوئے ساڑھے تین ماہ ہوچکے لیکن مولانا ممدوح کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
مولانا ابوالکلام آزادؔ یقیناً عظیم شخصیت کے مالک ہیں اس سے انکار بلکہ اس میں شبہ کرنے کی جرات بھی کوئی نہیں کرسکتا مگر مراسلت و گفتگو کا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں رتبہ،منصب اور مراتب کا امتیاز روا نہیں رکھا جاتا،اکابر،اصاغر کے خطوں اور نیاز ناموں کے جواب بھی عنایت فرما دیا کرتے ہیں اور ان کو اپنی محفلوں میں بار پانے کی اجازت بھی عنایت فرماتے ہیں،اگر ایسا نہ ہو اور بڑے آدمی صرف اپنے ہی جیسے بڑے آدمیوں سے ربط ضبط رکھنا پسند کریں اور چھوٹے آدمیوں کو لائقِ خطاب اور سزاوارِ التفات ہی نہ سمجھیں تو پھر بڑے آدمیوں کی زندگی خود ان کے لئے اجیرن بن کر رہ جائے،اس لئے کہ قریوں،قصبوں،شہروں اور ملکوں میں بڑے آدمی تو گنتی ہی کہ ہوتے ہیں اور کہیں کہیں تو ایک آدھ ہی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے گھروں میں بند بیٹھے رہیں کہ جب ان کے جوڑ کا کوئی آدمی آئے گا اسی وقت لب ہائے مبارک کو جنبش ہوگی،اگر بڑے آدمیوں کا یہی دستور رہتا تو تمدن اور ترقی،فیض و استفادہ،علم و اطلاع تحقیق و تفحص کی سعادتوں سے دنیا محروم رہتی۔
گاندھی جی کی مصروفیات کا بھلا کوئی ٹھکانا تھا اور ان کی شخصیت تو روزولٹ،چرچل اور اسٹالن سے بھی بلند تھی مگر وہ بھی معمولی معمولی لوگوں کے خطوں کا جواب دیا کرتے تھے،مسٹر کلیم الرحمٰن (جو منٹو سرکل ہوسٹل مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نگران تھے) مجھے ایک خط دکھایا تھا جو مسٹر ولبھ بھائی پٹیل آنجہانی نے ان کے ایک استفسار کے جواب میں بھیجا تھا،یہ خط دراصل گاندھی جی کے نام روانہ کیا گیا تھا اس مکتوب کا دفتری تعلق چونکہ سردار پٹیل نائب وزیراعظم حکومت سے تھا اس لئے مہاتما جی نے وہ خط مسٹر پٹیل کے پاس بھیجدیا اور مسٹر پٹیل نے مکتوب نگار کو جواب دیا اور خط پر خود ان کے دستخط ثبت تھے حالانکہ اس کام کو سردار پٹیل کے سکریٹری بھی انجام دے سکتے تھے۔
شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن،حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی،امیر شکیب ارسلان،عوام کے خطوں کا جواب دیا کرتے تھے،”برنارڈشا” اپنی انتہائی ادبی اور علمی مصروفیات کے باوجود خطوں کے جواب دینے میں بخیل نہیں تھا اور ظاہر ہے خط لکھنے والوں میں رڈیارڈ کپلنگ،ایچ جی ویلز اور چرچل جیسی شخصیت کے لوگ کہاں ہوسکتے تھے!میری سادگی پر شاید لوگ ہنسیں گے کہ میں نے لفافہ نہیں ایک جوابی کارڈ علامہ اقبالؔ مرحوم کی خدمت میں بھیجا،یہ میرے اوائل شباب کا واقعہ ہے میں ان دنوں اپنے وطن (کسیر کلاں،ضلع بلند شہر) میں تھا،اقبالؔ نے خود اپنے ہاتھ سے جواب لکھ کر روانہ فرمایا،مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آٹھ دن کے اندر اندر جواب آگیا تھا۔۔۔۔سنا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو خطوں کا جواب دینے میں خاص طور پر فیاض واقع ہوئے ہیں۔
میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بعض خطوں کے جواب نہیں دیئے جاتے،یعنی ایسے خطوط جن سے خواہ نخواہ کی چھیڑ اور نزاع مقصود ہو،یا جن کے جواب میں مکتوب الیہ کو بہت زیادہ کاوش کی ضرورت اور فرصت درکار ہو اور سرسری طور پر جواب دینے سے الجھنیں پیدا ہونے کا خطرہ ہو یا مکتوب نگار کے بارے میں مکتوب الیہ کو اس کا علم ہو کہ وہ اس سے کد،دشمنی اور عداوت رکھتا ہے اور اس مرسلت،گفت و شنید اور نامہ و پیغام کا مقصد کسی فتنہ کو ہوا دینا ہے۔۔۔۔۔۔۔مگر میرا خط اس طرح کا خط نہیں تھا مولانا ابوالکلام آزادؔ نے مجھ خاک نشین اور ہیچمدان کا شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا،میرا خط ان کے پاس بالکل ایک اجنبی شخص کی تحریر کی حیثیت سے پہونچا،میں نے ان سے کوئی علمی مسئلہ بھی دریافت نہیں کیا کہ اس کے لئے طویل فرصت درکار ہوتی اور نہ میں نے ان کے کسی علمی،ادبی،سیاسی اور مذہبی نظریہ پر کوئی تنقید لکھ کر ان کی خدمت میں بھیجی کہ اس کا سرسری جواب بہت سے فتنوں کا باعث ہوسکتا تھا،میرے استفسار کے جواب کے لئے مولانا ابولکلام آزادؔ کو ذرا سی بھی زحمت گوارا کرنے کی ضرورت نہ تھی،تین چار منٹ میں جواب لکھا یا لکھوایا جا سکتا تھا،مولانا موصوف حکومتِ ہند کے وزیر تعلیم ہیں،مددگاروں،کام کرنے والوں اور ماتحتوں کی ہر قسم کی سہولت بھی ان کو میسر ہے۔۔۔یہ باتیں اہم اس لئے تھیں کہ زبانوں سے نکل کر کاغذ پر آچکی تھیں ان کی حیثیت محض “افواہ” کی نہیں رہی تھی،یہ بات مولانا آزادؔ کے علم میں تھی،اس صورت میں غلط فہمی رفع کرنے کے لئے میرے سوالوں کا جواب دینا اور زیادہ ضروری تھا کہ جواب نہ دینے اور سکوت اختیار کرنے سے غلط فہمیاں اور مضبوط اور شاخ در شاخ ہوجائیں گی۔
پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ مولانا آزادؔ خطوں کے جواب دینے میں فطرتاً بے پروا واقع ہوئے ہوں اور خطوں کا جواب نہ دینا اور اس معاملہ میں بے نیازی برتنا ان کی عادت ہو “غبارِ خاطر” کے مقدمیں خود مولانا کے پرائیوٹ سکریٹری محمد اجملؔ صاحب نے لکھا ہے:
“مولانا کو سینکڑوں خط لکھنے اور لکھوانے پڑتے ہیں۔”
میں نے اوپر جو کچھ کہا ہے وہ مفروضات اور قیاس آرائیاں نہیں ہیں یہ واقعات ہیں جو بتاتے اور ظاہر کرتے ہیں کہ میرے نیاز نامہ کے جواب دینے سے مولانا ابوالکلامؔ کا پہلو تہی کرنا یقیناً “معنیٰ خیز” ہے اور مولانا آزادؔ نہیں چاہتے کہ ان چیزوں پر گفتگو ہو،یہ باتیں کھل کر سامنے آئیں اور واقعات بے نقاب ہوں۔
میں عند اللہ اور عندالناس ہر ذمہ داری سے بری ہوں کہ تحقیق و استفسار کی جو ممکنہ کوشش میرے بس میں تھی وہ کرچکا مولانا آزادؔ کی خدمت میں عریضہ اسی غرض کے لئے بھیجا تھا کہ یہ باتیں محض غلط اندیشی اور غلط فہمی پر اگر مبنی ہیں تو وہ اس کا ازالہ فرمادیں گے،اس سے اور اچھی کیا بات ہوسکتی ہے کہ کسی بڑے آدمی کی ذات اور شخصیت کے بارے میں کوئی غلط فہمی اس کے جیتے جی لوگوں میں پیدا ہو اور اس کو وہ خود دور کر دے مولانا آزادؔ کو زندگی ہی میں اس کا موقع ملا مگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ،کیوں؟ اس کا جواب آپ کو آگے ملے گا،شاید اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانے ہی میں وہ اپنی بہتری سمجھتے ہیں۔چند گزارشیں:
دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں،کیا عجب ہے کہ کوئی صاحب میری اس تحریر کو مسلم لیگ اور کانگریس کی کشمکش کا انتقامی نتیجہ قرار دیں،خدا جانتا ہے کہ لیگ اور کانگریس کی کشمکش سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے اور مولانا آزادؔ کو خدانخواستہ بدنام کرنے اور انکی بلند شخصیت کو مجرور کرنے کے لئے یہ کام کرنا تھا تو اس کا سب سے زیادہ مناسب وقت تقسیم ہند کا زمانہ تھا جبکہ کانگریس اور مسلم لیگ کے بہت سے جوشیلے کارکن ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے تھے،یہ بحث میں اس وقت چھیڑتا تو ایک طبقہ میں مقبولیت حاصل ہوسکتی تھی مگر اس قسم کی ضمیر فروشانہ مقبولیت کا تصور نہ اس وقت میرے ذہن میں تھا اور نہ اب ہے ،اس طرح کی اوچھی باتوں سے مجھے ہمیشہ نفرت رہی ہے۔
ہندوستان بٹ گیا،پاکستان بنے ہوئے بھی چار سال ہوچکے،لیگ اور کانگریس کی نزاع کبھی کی ختم ہوچکی،ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں تقسیم ہند سے قبل چاہے ان کی روش کچھ بھی رہی ہو مگر اب وہ مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس لئے پاکستانی مسلمانوں کے تمام مظلوم بھائیوں سے ہمدردی ہے اور وہ کسی کے بارے میں برا جذبہ نہیں رکھتے۔۔۔۔۔اگر میں پاکستان کے بجائے ہندوستان میں ہوتا اور ان واقعات کا انکشاف ہوتا تو میں وہاں بھی اس انکشاف کو منظرِ عام پر لے آتا۔
کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت اس انکشاف کی آخر کون سی ضرورت محسوس ہوئی!اس کے جواب میں عرض ہے کہ اسی وقت چونکہ یہ واقعات منکشف ہوئے اس لئے ان کو ظاہر کیا جارہا ہے اگر وہ اس سے پہلے معلوم ہوجاتے تو اسی وقت ان کو آشکار کردیا جاتا اور ہر وہ بات جو کسی واقعہ کی غلطی ظاہر کرتی ہو اس کے لئے کسی موسم وقت اور زمانہ کی قید نہیں ہے سوائے اس صورت کے جبکہ اس کے اظہار سے کسی بڑے فتنہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ اور کسی وقومی،دینی اور اخلاقی نقصان کا خطرہ ہو۔
آگر کوئی شخص اس بات کا اعلان کرے کہ “ماہرؔ القادری شراب پیتا ہے ” تو اس کے بارے میں کئی طرح کی رائیں ہوں گی،کوئی کہے گا کہ مسلمان کے کسی گناہ اور اخلاقی کمزوری کا اس طرح افشا نامناسب ہے،چھپانا،چسم پوشی سے کام لینا اور نظرانداز کردینا ہی بہتر ہے ،جو کوئی بندوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا ،کہیں سے آواز آئے گی کہ ممکن ہے کہ اپنی زندگی کے پچھلے دور میں ماہرؔ شراب پیتا ہو اور اس نے اب شراب خواری سے توبہ کرلی ہو،کیا کہنے والا اپنی آنکھ سے ماہرؔ کو شراب پیتے ہوئے دیکھ آیا ہے،کوئی کہے گا کہ فاسق اور فجار اسی قابل ہیں کہ ان کو رسوا کیا جائے تاکہ دوسروں کو عبرت اور نصیحت ہو۔۔۔۔۔غرض اس باب میں لوگوں کی مختلف رائے ہوں گی مگر اکثریت کا رجحان “پردہ پوشی” کی جانب ہی ہوگا،مگر میں یہ کہوں کہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پائی ہے اور حضرت مولانا انورؔ شاہ مرحوم نے اپنے ہاتھ سے میرے سر پر دستارِ فضیلت باندھی ہے” حالانکہ میں نے دیوبند کے مدرسہ میں کبھی تعلیم نہیں پائی اور جب وہاں میں نے پڑھا ہی نہیں تو دستارِ فضیلت اور سندِ تکمیل کا سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،ہاں!تو میری اس غلط بیانی کے سلسلہ میں سب کی ایک رائے ہی ہوگی،دو یا اس سے زیادہ رائیں ہو ہی نہیں سکتیں،جو شخص واقفِ حال ہوگا اس کا فرض ہوگا کہ وہ میری اس غلط بیانی کی تردید کرے!میری اخلاقی کمزوریوں کے اعلان و اظہار اور میری غلط بیانی کی تردید کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہے،اس کا حال ایسا ہی ہے جس طرح تاریخی غلطیوں اور علمی فروگزاشتوں پر احتساب کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔اب اگر کوئی شخص کسی کی شخصیت اور ذات و صفات پر ایمان بالغیب رکھتا ہو اور اس نے یہ طے ہی کر لیا ہو کہ “میں فلاں شخصیت کے بارے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتا ،کیسی ہی روشن دلیلیں کیوں نہ لائی جائیں مگر میری عقیدت اور حسنِ ظن میں کمی نہیں آسکتی تو اس ذہنیت کے افراد کو افسوس ہے میں مطمئن نہیں کرسکتا اور ان کی دشنام طرازیوں کو میں پہلے ہی معاف کئے دیتا ہوں،میرے مخاطب وہ اہلِ حق اور اربابِ بصیرت ہیں جو “حق” کو شخصیتوں سے بلند سمجھتے ہیں۔خاموش سفر(؟) :
جامعہ ازہر قاہرہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلیم پانے کی سب سے پہلی اطلاع مسٹر مہادیو ڈیسائی کی کتاب کے ذریعہ لوگوں تک پہونچی،مہادیو ڈیسائی(آنجہانی) کے نام اور کام سے لکھے پڑھے لوگ ناآشنا نہیں ہیں،وہ گاندھی جی کے نہایت معتمد علیہ رفیق شریک کار اور پرائیوٹ سکریٹری تھے،گاندھی جی کے صحافتی کاروبار انھی سے زیادہ تر متعلق تھے،مسٹر ڈیسائی انگریزی کے بہت اچھے انشاپرداز بھی تھے،انھی نے مولانا ابوالکلام آزاد کی “لائف”
MAULANA ABULKALAM AZAD
THE PRESIDENT OF THE INDIAN NATIONAL CONGRESS
A BIOGRAGHICAL MEMOIR
BY
MAHADEV DESAIلکھی ہے،اس کتاب پر “پیش لفظ”FOREWARD خود مہاتما گاندھی نے تحریر فرمایا ہے،یہ پیش لفظ بہت زیادہ مختصر ہے کل چھ سطریں ہیں اور ۱۸ مئی ۱۹۴۰ء تاریخ درج ہے،ایک صفحہ سے کچھ کم کا دیباچہ بھی ہے جس کے لکھنے والے مسٹر ہوریس الگزنڈر ہیں۔۔۔۔۔یہ اٹھاسی ۸۸ صفحوں کی کتاب ہے جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی کے واقعات کے ساتھ ساتھ بہت سے سیاسی مباحث بھی آگئے ہیں جن کا یہاں تذکرہ کیا جائے گا تو میں اپنے موضوع سے بہت دور چلا جاؤں گا،مولانا آزاد کے جو سوانح حیات اس کتاب میں درج ہیں ان کا مآخذ مولانا موصوف کی خود نوشت سوانح عمری “تذکرہ” اور خود ان کی زبان سے سنے ہوئے حالات ہیں۔
اس کتاب کے صفحہ ۸ پر یہ عبارت ہمیں ملتی ہے:
(ترجمہ:)
“سرسید احمد خاں نے قدامت پرستی کی طاقتوں کے خلاف مہم شروع کردی اور انگریزی اور جدید سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مسلم قوم سے پرجوش اپیل کی،میرے (یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے) والد بہرحال اس چیز کو گوارا نہ کرسکتے تھے،انھوں نے مجھے اور میرے بھائی کو قدیم طرز پر تعلیم دلائی،اس لئے میرے لئے کسی انگریزی اسکول میں بھیجے جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا،وہ چاہتے تھے کہ میں کسی نہ کسی طرح فاضل ترین علماء کی جماعت میں اپنا نام پیدا کروں،لہذا انھوں نے مجھے ۱۹۰۵ء میں اپنے ذاتی مصارف سے مصر بھیجا تاکہ قاہرہ کی مشہور یونیورسٹی الازہر میں عربی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکوں،میں وہاں دو سال تک متعلم رہا اور ۱۹۰۷ء میں ہندوستان واپس آیا”اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ۱۹۰۵ء میں مصر تشریف لے گئے اور دوسال یعنی ۱۹۰۷ء تک وہاں قیام فرمایا۔۔۔۔۔اب میں اپنی تحقیق کی بنا پر مولانا موصوف کی زندگی کی مصروفیت کے چند سال تاریخی سنین کے ساتھ یہاں پیش کرتا ہوں،میری اس تحقیق کا نقطہء آغاز ۱۹۰۲ء ہے!
جولائی ۱۹۰۲ء میں مولانا ابوالکلام آزاد کلکتہ میں موجود تھے،اسی مہینہ میں شاہ ایڈورڈ ہفتم کے جشنِ تاج پوشی کے سلسلہ میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا تھا جس میں مولانا موصوف نے بھی مدحیہ قطعے پڑھے تھے۔۔۔۔فرماتے ہیں:
شد تخت نشیں بہ تخت انگلینڈ
خوش بخت شد است بحتِ انگلینڈ
یعنی ایڈورڈ شاہ ذی جاہ
شد تخت نشیں بہ عزت و جاہہوئی لندن میں از فضل الٰہی
نہایت شان سے جب تاج پوشی
کہا آزادؔ نے بڑھ کر ادب سے
مبارک شاہ کو اب تاج پوشیاس مشاعرہ کے صدر جناب رنجور عظیم آبادی تھے اور مولوی غلام یسین آہؔ نے تقریر کی تھی،اخبار “الپنج” بانکی پور(مورخہ ۵جولائی۱۹۰۲ء)میں اس مشاعرے کی کاروائی تفصیل کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔
۱۹۰۳ء اور ۱۹۰۴ءمیں مولانا آزادؔ کلکتہ سے “لسان الصدق” نکالتے تھے،۱۹۰۵ء اور ۱۹۰۶ء میں الندوہ کے ایڈیٹر رہے اور ۱۹۰۶ء کے بعد ۱۹۰۸ء تک “الوکیل” (امرتسر) کی ادارت مولانا ممدوح سے متعلق رہی۔۔۔۔یہ ہے ۱۹۰۲ء سے لیکر ۱۹۰۸ء تک مولانا ابوالکلام آزادؔ کے ہندوستان میں قیام اور ان کی مصروفیات کی تفصیل!مسٹر مہادیو ڈیسائی نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کی ان سنین سے کسی طرح مطابقت نہیں ہوتی،دو چار مہینہ کا فرق اور اختلاف ہوتا تو اسے کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر فِٹ کیا جاسکتا تھا مگر یہاں تو دوسال کی مدت کا فرق ہے جس کی کوئی توجیہ اور تاویل ہماری سمجھ میں نہیں آتی،مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جن دوسالوں میں مولانا آزادؔ کا قاہرہ میں قیام بتایا جاتا ہے ان میں وہ الندوہ اور الوکیل کی ایڈیٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔
مولانا ابوالکلام آزادؔ نے “تذکرہ” میں اپنے خاندان کا جس انداز میں ذکر فرمایا ہے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے خانوادے میں مدتوں ارشاد و تصوف کی شمعیں روشن رہی ہیں،اس لئے ان سنین اور واقعات کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے مولانا کے خاندانی تصرفات ہی سے مدد لی جاسکتی ہے،یعنی یہ فرض کرلیا جائے کہ مولانا آزادؔ بہ وقتِ واحد ہندوستان میں بھی موجود تھے اور قاہرہ کے جامعہ ازہر میں بھی تعلیم پارہے تھے۔۔۔۔۔۔اس کے سوا اور کوئی تاویل،توجیہ اور تطبیق ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔
کسی شخص سے اظہارِ واقعہ میں کسی سبب سے بھول چوک ہوجائے اور وہ اس کا ایچ پیچ کے ساتھ نہیں،صاف اور واضح لفظوں میں اقرار کرلے تو معاملہ وہیں ختم ہوجاتا ہے لیکن غلط بیانی کو صحیح اور درست ثابت کرنے کی کوشش جب بھی کی جائے گی،کچھ اور غلط بیانیوں کا اضافہ ہوجائے گا،یہی چیز یہاں مشاہدہ میں آرہی ہے۔
مولانا ابوالکلام آزاد کے سفر مصر و عراق کے بارے میں چہ میگوئیاں شروع ہوئیں اور یہ باتیں تحریر تک میں آگئیں تواس حاشیہ آرائی کی ضرورت محسوس کی گئی،۱۶فروری۱۹۴۹ء کا “نیا ہندوستان” ہمارے سامنے ہے،جس میں ایک مضمون کا عنوان “امام الہند” ہے،اس مضمون کے شروع میں یہ نوٹ درج ہے:
“کئی سال کی کوشش و محنت سے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی سوانح حیات کا حصہ اول مرتب کیا گیا تھا اور اس میں شک نہیں کہ بے انتہا مصروفیت کے باوجود امام الہند نے ہمارے مرتب کردہ سوالات کے تحریری و زبانی ضوابات بھی ازراہِ کرم عنایت فرمائے لیکن جب ترتیب کے بعد اس کی اشاعت کا سوال آیا تو امام الہند نے سختی سے روکا اور فرمایا کہ کسی شخص کی سوانح حیات مکمل طور پر زندگی میں مرتب نہیں ہوسکتی ،اس لئے فی الحال اس ارادہ کو ملتوی کردیا جائے،اس کا ایک حصہ ہدیہ ناظرین کیا جارہا ہے اور ان شاءاللہ کبھی کبھی پیش ہوتا رہے گا۔۔۔۔شاہدؔ شیروانی”
اس شذرہ کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کے سوانح حیات کا آغاز ہوتا ہے،اس مقالہ کے دوسرے پیراگراف کے شروع کے جملے یہ ہیں:
“آپ کا بچپن مکہ اور مدینہ میں بسر ہوا،مدینہ میں ان کے والد کا مکان دینی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا،ابتدائی تعلیم آپ نے والد سے حاصل کی آپ نے قاہرہ کی مشہور عالم یونیورسٹی الازہر میں میں بھی تعلیم حاصل کی ہے،چودہ سال کی عمر میں آپ نے جامعہ الازہر میں علوم مشرقی کا نصاب پورا کرلیا تھا۔۔۔۔”
یہاں پہونچ کر “کر لیا تھا” پر یہ نشان (۱) ثبت ہے اور ذیل کا فٹ نوٹ درج ہے،جسے بلفظہ نقل کرتے ہیں:
“یہ غلط ہے کہ مولانا نے جامعہ ازہر قاہرہ میں تعلیم پائی ہے،مسٹر آصف علی کی طرح دوسرے سوانح نگاروں مہادیوڈیسائی وغیرہ نے بھی دھوکا کھا ہے،۱۹۰۶ء میں مصر وغیرہ گئے تھے،ظاہر ہے کہ اس وقت ۱۸سال کی عمر تھی اور ہندوستان کی صحافتی و علمی دنیا میں اپنے معرکۃ الارا مضامین کی بدولت کافی شہرت و وقعت حاصل کرچکے تھے،تکمیل تعلیم ۱۵،۱۶ سال کی عمر میں ہی ہوچکی تھی،یہ ضرور ہے کہ مولانا شبلی نعمانی مرحوم کی طرح اکابر جامعہ ازہر اور مفتی محمد عبدہ کے “دارالعلوم” کے شیوخ سے استفادہ کیا اور ان کی علمی مجالس کی زینت بنے،اس کی تحقیق ۲۳جنوری ۱۹۴۷ء کی ایک ملاقات میں خود امام الہند سے کرچکا ہوں،اس سفر میں برادرِ گرامی غلام یسین آہ مرحوم بھی امام الہند کے ساتھ تھے مگر وہ عراق سے واپس آگئے اور مولانا ۱۹۰۷ء میں ایک سال کی سیر و سیاحت کے بعد واپس ہوئے۔۔۔شاہد شیروانی”
مولانا ابوالکلام آزاد کے سفرِ مصر کا واقعہ تو مسٹر مہادیو ڈیسائی کی کتاب اور جناب شاہد خاں شیروانی کے اس شذرہ میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے،لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہوجاتا ان میں دو زبردست اختلافات موجود ہیں۔ایک سنِ تاریخ کا اختلاف اور دوسرا مقصد سفر اور وہاں کی مصروفیات کا اختلاف!مہادیو ڈیسائی نے لکھا ہے کہ مولانا ۱۹۰۵ء میں مصر تشریف لے گئے تھے اور شاہد شیروانی اس سفر کا سنہ۱۹۰۶ء بتاتے ہی،ڈیسائی لکھتے ہیں کہ مولانا جامعہ ازہر میں عربی کی تعلیم پانے کی غرض سے گئے تھے اور دوسال تک اسی سلسلہ میں وہاں قیام کیا اور شاہد شیروانی کا بیان ہے کہ مولانا نے جامعہ ازہر میں سرے سے تعلیم ہی نہیں پائی ہاں!یہ ضرور ہے کہ “اکابر جامعہ ازہر اور مفتی محمد عبدہ کے دارالعلوم کے شیوخ سے استفادہ کیا اور ان کی علمی مجالس کی زینت بنے۔۔۔۔”
یہ عجیب و غریب اختلاف اور تضاد ہے،عجیب و غریب ہم اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ڈیسائی اور شاہد شیروانی نے جو کچھ لکھا ہے خود مولانا ابوالکلام آزاد کی زبان سے سن کر لکھا ہے،آخر ہم ان دونوں میں سے کس کے بیان کو صحیح سمجھیں۔۔۔۔ایک واقعہ یا ایک بات بہت سے راویوں سے جب سنی جاتی ہے یا اصل شخص اور اس کے راویوں کے درمیان مدت اور زمانہ کے اعتبار سے فرق اور طول ہوتا ہے تو اس قسم کے اختلافات کے لئے گنجایش نکل سکتی ہے،مگر یہاں تو راویوں کا سلسلہ ہی درمیان میں نہیں ہے،اصل شخص کہتا ہے اور سننے والا روایت کرتا ہے اور یہ روایتیں اس شخص کی زندگی ہی میں پھیلتی ہیں،اس اعتبار سے روایات کا یہ تضاد اور اختلاف یقیناً عجیب و غریب ہے
مسٹر مہا دیو ڈیسائی کی کتاب ۱۹۴۰ء میں شائع ہوئی تھی،ناممکن ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسے نہ پڑھا ہو،جب وہ لکھی جارہی تھی اس کا بھی مولانا کو علم تھا،مسٹر ڈیسائی نے مولانا کے سفرِ مصر کے سلسلہ میں اگر کوئی غلط بات لکھ دی تھی تو اس کی ہاتھ کے ہاتھ تردید کردینی چاہیئے تھی،مگر نہیں کی گئی۔۔۔۔جب یہ بات موضوعِ بحث بنی تو ۱۹۴۷ء میں اس کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اسے شاہد شیروانی کے حوالہ سے اوپر درج کیا جاچکا ہے۔
یہ تو مولانا ابوالکلام آزاد کے سفرِ مصر کی داستان رہی،اب عراق،ایران اور لبنان کے سفر کا حال سنئے۔۔۔۔
“شکر کے معاملہ میں اگر کسی گروہ کو حقیقت آشنا پایا تو وہ ایرانی ہیں اگرچہ چائے کی نوعیت کے بارے میں چنداں ذی حس نہیں مگر یہ نکتہ انھوں نے پالیا ہے،عراق اور ایران میں عام طور پر یہ بات نظر آئی تھی کہ چائے کے لیے قند کو جستجو میں رہتے تھے اور اسے معمولی شکر پر ترجیح دیتے تھے کیونکہ قند صاف ہوتی ہے اور وہی کام دیتی ہے جو موٹے دانوں کی شکر سے لیا جاتا ہے،نہیں کہہ سکتا کہ اب وہاں کیا حال ہے؟”(غبارِ خاطر صفحہ ۱۷۹،۱۸۰)
قند اور چائے کے بعد،موسم کا ذکر فرماتے ہیں:
“غالباً ۱۹۰۵ء کی بات ہے کہ بمبئی میں مرزا فرصت شیرازی صاحب آثار العجم سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا وہ برسات کا موسم پونا میں بسر کر کے لوٹے تھے اور کہتے تھے کہ پونا کی ہوا کے اعتدال نے ہوائے شیراز کی یاد تازہ کردی
اے گل بہ تو خر سندم تو بوئے کسے داری!
میرا ذاتی تجربہ معاملہ کو یہاں تک نہیں لے جاتا لیکن بہرحال شیراز میں مسافر تھا اور مرزا موصوف صاحب البیت تھے و صاحب البیت ادری بما فیہا!” (غبارِ خاطر ۱۹۳،۱۹۴)
شیراز کے بعد لبنان کا ذکر آتا ہے،لکھتے ہیں:
“لوگ گرمیوں میں پہاڑ جاتے ہیں کہ وہاں کی گرمیوں کا موسم بسر کریں،میں نے کئی بار جاڑوں میں پہاڑوں کی راہ لی کہ وہاں جانے کا اصلی موسم یہی ہے،متنبیؔ بھی کیا بے ذوق تھا کہ لبنان(اگر متنبیؔ کا اور حافظ کے شعروں کا ذکر کرنا تھا تو اس کے لئے لبنان اور شیراز و قزوین کی سیر و سیاحت کی افسانہ طرازی سے ہٹ کر،دوسرا پیرایہ بھی مولانا اختیار فرما سکتے تھے،مولانا آزاد فطرتاً خوش ذوق اور نفاست پسند واقع ہوئے ہیں،ایران کے چمن زاروں کی سیرونظارگی کو اس پر شاہد بنانے کی کوئی خاص ضرورت تو نہ تھی۔ماہرؔ) کے موسم کی قدر نہ کرسکا میری زندگی کے چند بہترین ہفتے لبنان میں بسر ہوئے ہیں۔”(غبارِ خاطر صفحہ ۱۹۸)
ایران کے چمن زاروں میں مرغانِ خوش الحان کی نغمہ سنجی کا افسانوی احوال پڑھنے کی چیز ہے:
“حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایک شخص نے شیراز یا قزوین کے گل گشتوں کی سیر نہ کی ہو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ حافظ کی زباں سے یہ شعر کس عالم میں ٹپکے تھے:
بلبل بہ شاخِ سرو بہ گلبانگ پہلوی
می خواند دوش درسِ مقامات معنوی
یعنی بپا کہ آتشِ موسیٰ نمود گل
تا از درخت نکتہ تحقیق ۔۔۔۔
مرغانِ باغ قافیہ سنجدو بذلہ گو
تا خواجہ مے خورد بہ غزلہائے پہلوی
یہ جو کہا کہ مرغانِ باغ “قافیہ سنجی” کرتے ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہے،واقعہ ہے میں نے ایران کے چمن زاروں میں ہزار کو قافیہ سنجی کرتے خود سنا ہے۔(غبارِ خاطر صفحہ ۲۳۶)گمنام سیاحت
جہاں تک ہماری تحقیق اور معلومات کا تعلق ہے،ایران،عراق اور لبنان کے سفر کا ذکر “غبارِ خاطر” کی تصنیف پہلے اور کہیں نہیں ملتا،مسٹر ڈیسائی نے اپنی کتاب میں سفرِ مصر کا تو ذکر کیا ہے اور مولانا آزاد کے زبانی بیان کے حوالہ سے کیا ہے مگر عراق،ایران اور لبنان کی سیر و سیاحت کا کہیں ذکر تو کیا نام تک نہیں لیا۔احمد نگر کے قلعہ میں جب مولانا نظر بند تھے اور “غبارِ خاطر” کے خطوط لکھ رہے تھے،اس زمانہ میں عراق،ایران اور لبنان کے سفر کا ایکاایکی کس طرح کشف ہوگیا،اس سے پہلے لبنان کے پہاڑوں کے مناظر اور شیراز و قزوین کے چمن زاروں میں مرغانِ خوش الحان کی نغمہ سنجیاں،آخر مولانا کے قلب و دماغ کے کس گوشہ میں بند تھیں۔۔۔شاید اسیری اور قید و بند میں حافظہ ضرورت سے زیادہ تیز،حساس اور جدت طراز ہوجاتا ہے۔
مصنفوں اور انشاپردازوں کی یہ عادت ہے کہ جب انھیں کوئی سفر درپیش آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی عنوان سے غیر ممالک کی سیر و سیاحت کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور وہ انشاپرداز جو رسالوں اور اخباروں کے ایڈیٹر بھی ہوں وہ تو اپنے سفر کے ذکر سے باز آ ہی نہیں سکتے۔
علامہ شبلی نعمانی نے مصر اور ترکی کا سفر فرمایا تو اس سفر کا حال کتابی صورت میں شائع کیا،رائیس الاحرار مولانا محمد علی مرحوم اور مولانا سید سلیمان ندوی کے سفرِ انگلستان کا حال ان کے خطوں سے معلوم ہوتا ہے،سر شیخ عبدالقادر مرحوم کا سفرنامہ ہماری نظر سے گزرا ہے،اور تو اور پیسہ اخبار کے ایڈیٹر مولوی محبوب عالم انگلستان گئے تھے تو ان تک نے اپنے سفر کے حالات لکھ کر چھپوائے تھے،بڑے آدمیوں کے ساتھ اپنا ذکر مناسب نہیں سمجھتا مگر ضرورت آپڑی ہے تو عرض کرتا ہوں کہ میں نے ۱۹۳۳ء میں عراق کا سفر کیا تھا اور وہاں سے واپس آکر درجنوں مضامین لکھے اور “بغداد کے چمن میں ایک شام” کے عنوان سے ایک نظم بھی کہی جو میرے مجموعہ کلام میں موجود ہے!آخر مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے سفر اور سیاحت کا ذکر کیوں نہیں فرمایا اور جو ذکر ان کے حوالہ سے لوگوں تک پہنچا ہے وہ چند سال کی مدت کے اندر ہی کا ہے،اتنی مدت تک ان واقعات پر سکوت اور گمنامی کے پردے آخر کس لیے پڑے رہےاور ان مشاہدات اور واردات کو “شدید راز” کی طرح کیوں چھپایا گیا۔
الندوہ،الوکیل اور الہلال کے صفحات مولانا آزاد کے ذکر سے آخر کیوں خالی ہیں اور یہ کس قسم کی گمنام سیاحت اور چپ چاپ سفر ہے کہ ان کے معاصرین اور دوستوں کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی،نہ اس زمانے کے یا بعد کے کسی اخبار میں مولانا کے سفر کا کوئی حال،اطلاع،خبر یا تفصیل چھپتی ہے اور نہ مولانا ہندوستان میں اپنے کسی دوست اور عزیز کو مصر،عراق،ایران اور لبنان سے کوئی خط لکھتے ہیں۔۔۔۔اور پھر حیرت بالائے حیرت یہ ہے کہ مولانا آزاد اپنی خودنوشت سوانح عمری “تذکرہ” میں اپنے بارے میں اور تو سب کچھ لکھتے ہیں مگر اس سیر و سیاحت کا حال نہیں لکھتے۔
بعض لوگ یقیناً اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی جبلت پر تواضع اور انکسار کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اپنے بارے میں بہت ہی کم کہتے ہیں،مگر مولانا آزاد کا “تذکرہ” گواہ ہے کہ وہ منکسرالمزاج لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں،اپنے خاندان اور اپنے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے،بڑے آدمیوں میں سے شاید بہت ہی کم نے اپنے متعلق اتنا کچھ لکھا ہو،پھر جو شخص “چائے” کے ذکر میں صفحے کے صفحے لکھ سکتا ہے اور پرندوں کے تذکرے کو ایک مستقل باب میں پھیلا سکتا ہے،(“غبارِ خاطر” میں یہ تمام تفصیل ہوجود ہے!ماہرؔ) وہ مصر،عراق،ایران اور لبنان کی سیاحت کرتا ہے اور اس کی زبان بالکل گنگ اور اس کا قلم قطعاً ساکن رہتا ہے اور سیر و سیاحت کے حالات قلم بند کرنے کا کوئی ولولہ ہی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا،ایک مدت گزر جانے کے بعد ذکر بھی فرمایا تو اس قدر تشنہ بلکہ استعاروں اور افسانوی انداز میں کہ پڑھنے والے سیر و سیاحت پر مطلع بھی ہوجائیں اور بات زیادہ کھلنے بھی نہ پائے!
حیرت ہے کہ مولانا آزاد ایران کا سفر کریں،شیراز اور قزوین بھی جائیں،اور وہاں کی صرف چائے،قند اور مرغانِ چمن کی نغمہ سنجی کا یوں ہی سا ذکر کے رہ جائیں،کیا پارس کے اکابر،علماء،مشاہیر،آثارِ قدیمہ،کتب خانے،بازار،علمی درسگاہیں،بیستون،رکنا باد،گلگشت،مصلا اور سب سے بڑھ کر سیاسی حالات۔۔۔۔۔ان میں سے کوئی چیز بھی موضوعِ نگارش اور اور عنوانِ اظہار بننے کے قابل نہ تھی ان میں سے ہر “عنوان” سرسری نہیں تفصیل کا محتاج بلکہ مستحق تھا۔۔۔مولانا آزاد فارسی شاعری سے غیر معمولی شغف رکھتے ہیں اس ذوق کی فراوانی کا یہ عالم ہے کہ فارسی شعر استعمال کرنے کے لئے نثر میں تمہید باندھتے اور زمین ہموار کرتے ہیں مگر ایران جاکر وہاں کے کسی شاعر(رہا مرزا فرصتؔ شیرازی کا ذکر،سو ان سے مولانا بمبئی میں پہلے ہی مل چکے تھے۔ماہرؔ) سے نہیں ملتے،اور جو ملتے ہیں تو اس کا ذکر نہیں فرماتے،یہ سکوت بھی قیامت کا سکوت ہے!
کسی واقعہ کی تحقیق کے دو ذریعے ہیں روایت اور درایت،ہم نے ان دونوں ذریعوں سے کام لیا ہے،اور ہم اس نتیجہ پر پہونچے ہیں کہ مولانا آزادؔ کے مصر،عراق،ایران اور لبنان کا سفر ایک افسانہ نگار کی شوخیء فکر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔دلی۔۔۔یاکھیم کرن
مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمت میں جب راقم الحروف نے خط بھیجا تھا،تو میں واقعات کی تحقیق ہی کر رہا تھا،واقعات پوری طرح کھلے نہ تھے اور یہ تحقیق نامکمل تھی،بہرحال تحقیق کا سلسلہ جاری رہا اور بہت سی دوسری باتیں بھی معلوم ہوئیں جن کا ذکر نہ کروں گا تو یہ مضمون ادھورا رہ جائے گا۔
مولانا آزاد اپنے کو الہلال میں “دہلوی” لکھا کرتے تھے مگر دہلی نہ ان کا مولد ہے اور نہ ان کا منشاء ہے،مسٹر مہادیو ڈیسائی نے لکھا ہے(اور جو لکھا ہے اس کا مآخذ مولانا آزاد کا “تذکرہ” اور ان کا زبانی بیان ہے) کہ مولانا ۱۸۸۸ء میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور دس سال تک وہیں رہے،۱۸۹۸ء میں ان کے والد مولانا خیرالدین کلکتہ میں آکر مقیم ہوگئے اور مولانا آزاد بھی ان کے ساتھ چلے آئے اور کلکتہ ہی میں درسِ نظامی کی تکمیل کی۔۔۔دہلی سے مولانا آزاد کی وجہِ نسبت یہ البتہ ہوسکتی ہے کہ بقول مسٹر ڈیسائی ان کے والد دہلی میں رہتے تھے،۱۸۵۷ء کے آشوبِ غدر کے بعد انھیں دہلی چھوڑنی پڑی اور اپنے مرید نواب یوسف علی خاں والی رامپور(نواب یوسف،مولانا آزاد کے والدِ بزرگوار مولانا خیرالدین کے مرید اور عقیدت مند تھے یہ بھی تحقیق طلب ہے!)کے پاس چلے گئےاور نواب صاحب نے مولانا خیرالدین کے بمبئی جانے کا انتطام کردیا،بمبئی سے وہ مکہ چلے گئے۔
عرض کرنا یہ ہے کہ مولانا نے اپنے خاندان حالات کے سلسلہ میں بہت کچھ لکھا ہے مگر انہوں نے کھیم کرن کا نام نہیں لیا،اس مضمون کے پڑھنے والے متحیر ہوں گے کہ یہ کھیم کرن کیا بلا ہے؟سنئے،قصور(مغربی پنجاب) سے امرت سر ریل کےذریعہ جاتے ہوئے ایک قصبہ کھیم کرن پڑتا ہے مولانا آزاد کے دادا جن کا نام عمردین اور عرف “چھیکڑی” تھا کھیم کرن ہی میں بودوباش رکھتے تھے،مولانا خیرالدین کے بڑے بھائی یعنی مولانا آزاد کے تایا کا نام امام دین تھا،عمر دین نے کھیم کرن کی سکونت ترک کردی تھی،مگر اس کا پتا نہ چل سکا کہ وہاں سے وہ پھر کس جگہ جاکر بس گئے،مولانا آزاد کی جب شہرت ہوئی تو وہاں کے لکھے پڑھے لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ ہماری بستی کے عمردین کے پوتے نے اتنا نام پیدا کیا ہے!کوئی چاہے تو کھیم کرن جاکر اس واقعہ کی آج بھی تحقیق کرسکتا ہے۔رکن المدرسین
مولانا آزاد نے اپنے “تذکرہ” میں لکھا ہے کہ ان کے اسلاف کو “رکن المدرسین” کا معزز عہدہ شاہانِ مغلیہ نے عطا فرمایا تھا(اس وقت تذکرہ میرے سامنے نہیں ہے،اپنے حافظہ کے اعتماد پر روایت بالعنیٰ کررہا ہوں)۔۔۔۔۔۔اپنے محدود مطالعہ پر اکتفا اور اعتماد نہ کرتے ہوئے میں نے متعدد حضرات سے جو ہندوستان کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں “رکن المدرسین” کے بارے میں دریافت کیا مگر سب نے لاعلمی ظاہر کی،ہر ایک نے یہی کہا کہ کسی تاریخ کی کتاب میں اس نام کا کوئی علمی عہدہ ہماری نظر سے نہیں گزرا،میں عرض کرتا ہوں کہ اول تو “رکن المدرسین” کی یہ ترکیب ہی غلط ہے،”رکن العلم” یا اسی قبیل کی کوئی ترکیب ہونی چاہئے تھی،”رکن المدرسین” کا انگریزی ترجمہ
Pillar of teachers
صحیح ہے،مگر مسٹر مہادیوڈیسائی نے انگریزی ترجمہ میں اصل لفظ کی معنوی غلطی کو دور کرتے ہوئے اس کا ترجمہ
Pillar of learnings
کیا ہے۔۔۔اس کے علاوہ اگر شاہانِ مغلیہ کے یہاں واقعی “رکن المدرسین” کوئی معزز علمی عہدہ اور منصب تھا تو مختلف زمانوں میں اس عہدہ کے زیادہ مستحق عبدالنبی،مخدوم الملک،ملا عبدالقادر بدایونی،ابوالفضل،فیضیؔ،شیخ عبدالحق محدث دہلوی،ملا جیون،ملا عبدالحکیم سیالکوٹی،ملا نظام الدین اور حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبدالرحیم اور دوسرے علماء و اکابر تھے۔“الہلال” کے مضامین
سہ روزہ “مدینہ” (بجنور) کا ۱۷ اگست ۱۹۵۱ء کا شمارہ میرے سامنے ہے صفحہ(۲) پر جو “اداریہ” ہے اس عنوان ہے:
“خانقاہِ عظمتِ اسلام”
راجدھانی میں امام الہند کے چند لمحے
اس مضمون میں “مدینہ” کے ایڈیٹر نے مولانا آزاد سے اپنی ملاقات کا حال تفصیل کے ساتھ لکھا ہے،جس کا ایک حصہ درج ذیل کیا جاتا ہے:
“۱۹۴۷ء میں مولانا حیدرزمان صدیقی صاحب کی کتاب “اسلامی نظریہ سیاست” مکتبہ دین و دانش بانکی پور(پٹنہ) سے شائع ہوئی ہے،مولانا سید سلیمان ندوی نے اس کا دیباچہ لکھا،دیباچہ کے حاشیہ پر ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ “الہلال” میں چونکہ مضمون نگاروں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے،اس لئے الہلال کے مضمونوں کے مجموعے شائع کرنے والوں نے بلا تحقیق ہر مضمون کو مولانا ابوالکلام صاحب کی طرف منسوب کردیا حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔۔”الحریۃ فی الاسلام” “تذکار نزولِ قرآن”،”حبشہ کی تاریخ کا ایک ورق”،”قصص بنی اسرائیل”،مشہدِ اکبر”(یہ ان چند مضامین میں سے ایک مضمون ہے جس پر “الہلال” کو ناز ہے!ماہرؔ) وغیرہ میرے مضامین ہیں۔
۱۹۵۰ء میں مکتبہ علم و حکمت بہار شریف (پٹنہ) نے سید صاحب کے مضامین کا حصہ اول شائع کیا ہے اس مجموعہ میں وہ مضمون شامل ہے جسے “الہلال” ایجنسی لاہور نے کئی سال پہلے “حقیقتِ الصوم” نامی پمفلٹ کی شکل میں شائع کیا تھا۔۔۔۔میں نے (یعنی ایڈیٹر اخبار مدینہ نے) اس بات کا ذکر کیا تو مولانا(آزاد) نے فرمایا۔۔۔”ہاں!سید سلیمان صاحب نے میرے ساتھ “اسسٹنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے چھ مہینہ تک کام کیا ہے،وہ ترجمے بھی کرتے تھے اور مضامین بھی لکھتے تھے،خیر اگر وہ مضامین کو اپنا بتاتے ہیں تو میری طرف سے آپ مدینہ میں اعلان کردیجئے کہ وہ مضمون سیدصاحب کا ہے،کچھ مضامین اگر میرے نام کے نہ ہوئے تو میرے بھائی!اس میں میرا بگڑتا کیا ہے؟”
“آخری جملہ کہہ کر مولانا(آزاد) نے اپنے مخصوص انداز میں جس کی گونج اظہارِ بےنیازی کے موقعہ پر سنائی دیتی ہے ایک قہقہہ لگایا اور پھر سگریٹ کا ایک کش لیا۔۔۔”
اخبارِ مدینہ کے اداریہ کا جو اقتباس اوپر درج کیا گیا ہے اس سے معاملہ کی نوعیت شاید قارئین سمجھ گئے ہوں گے،اور نہ سمجھے ہوں تو ان کو سمجھانے کے لئے میں تفصیل پیش کئے دیتا ہوں
مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار “الہلال” جب نکلتا تھا تو دوسرے اہلِ علم اور اربابِ قلم بھی مولانا موصوف کے شریکِ کار اور معاونین تھے،غیر زبانوں کے مضامین کے اردو ترجمے کا کام بھی انجام دیتے تھے اور اپنے اوریجنل مضامین بھی لکھتے تھے،ان مضامین پر عام طور سے ترجمہ کرنے اور لکھنے والوں کا نام درج نہیں ہوتا تھا۔
ناشرین نے الہلال کے مضامین کا انتخاب کتابی صورت میں جب شائع کیا تو انھوں نے ہر اس مضمون کو جس پر کسی مترجم اور مصنف کا نام نہ تھا مولانا ابوالکلام آزاد ہی کا مضمون سمجھا اور ان سے منسوب کردیا،بےچارے ناشرین کی اس میں کوئی غلطی نہ تھی،خود مجھے بھی اسی طرح کا دھوکا ہو چکا ہے،جب آصفیہ ہائی اسکول حدرآباد دکن کی لائبریری سے “الہلال” کا پورا فائل میں نے لیکر پڑھا تو جن مضامین پر کسی کا نام نہ تھا ان کو میں نے مولانا آزاد ہی کے زورِ قلم اور کاوشِ تحقیق کا نتیجہ سمجھا۔
ہوسکتا ہے “الہلال” کے مضامین کے یہ مجموعے مولانا ابوالکلام آزاد کی نگاہ سے نہ گزرے ہوں اور وہ اس سے بے خبر رہے ہوں مگر ان مضامین کے سلسلہ میں مولانا موصوف نے اخبار”مدینہ” کے فاضل مدیر کو جس انداز میں جواب عنایت فرمایا ہے،اس کی کم سے کم مولانا آزاد سے توقع نہ تھی۔۔۔۔اتنی بلندی،اتنی پستی!حیرت اور افسوس بھی!
مولانا سید سلیمان ندوی نے مولانا آزاد کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا تھا بلکہ انھوں نے الہلال کے مضامین کے مجموعے شائع کرنے والوں کو ٹوکا تھا “مدینہ” کے ایڈیٹر جب ان باتوں کو مولانا آزاد کے علم میں لائے تھے تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیئے تھا کہ “جن مضامین کا سید صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ واقعی انھی کے ہیں” یہ بات کسی ایچ پیچ طنز اور ابہام و تشابہ کے بغیر دوٹوک انداز میں کہہ دینی چاہیئے تھی اور مولانا آزاد اگر اپنے احساسِ برتری اور وقار و تشخص کا اظہار بھی ضروری سمجھتے تو اس جواب کے ساتھ اس قسم کے لفظوں کا اضافہ بھی فرماسکتے تھے۔۔”سید صاحب کے جو مضامین الہلال میں چھپے ہیں،میری ذات سے ان کی نسبت میرے لئے ذرا بھی باعثِ فخر نہیں ہے۔۔!۔۔۔۔۔۔مگر جواب میں فرمایا یہ گیا۔۔۔۔”خیراگروہمضامینکواپنابتاتےہیںتومیریطرفسےآپمدینہمیںاعلانکردیجئےکہوہمضمونسیدصاحبکاہے،کچھمضامیناگرمیرےنامکےنہہوئےتومیرےبھائی!اسمیںمیرابگڑتاکیاہے!”
مولانا آزاد کا یہ جواب اپنی جگہ ایک عجیب و غریب قسم کا مغالطہ ہے،جیسی ضرورت آن کر پڑے “انکار” اور “اقرار” “نفی” اور “اثبات” کے دونوں پہلو پیدا کئے جاسکتے ہیں،جواب صاف بھی ہے،اور گول مول بھی ہے،یہ سلیمان ندوی پر طنز بھی ہے اور اپنی فیاضی اور فراخدلی کا ثبوت بھی ہے کہ “وہ مضامین ہیں تو میرے،مگر سید صاحب اپنے بتاتے ہیں تو ان کے ہی سہی۔۔۔۔”اور پھر آخری جملہ فرما کر مولانا آزاد ایک قہقہہ لگاتے ہیں!
اس پوری بحث کو ذہن میں رکھ کر اب ذرا علامہ شبلی نعمانی کے دو خط ملاحظہ فرمائیے،جو مولانا عبدالسلام ندوی کے نام لکھے گئے تھے:
۔۔۔۔۔۔۔تم الہلال میں جاؤ مضائقہ نہیں یہ شرط کرلو کہ تم الہلال میں جذب نہ ہوجاؤ۔اس میں جو کچھ لکھو اپنے نام سے لکھو ورنہ تمھاری زندگی پر بالکل پردہ پڑجائے گا اور آئندہ ترقیوں کے لئے مضر ہوگا۔
شبلیؔ۔۔۔الہ آباد ۳مارچ۱۹۱۴ء
(مکاتیب شبلیؔ،حصہ دوم،مکتوب نمبر۵،صفحہ۱۵۲)
2
۔۔۔۔۔۔۔۔تمہارے مضامین دیکھتا ہوں،مولوی ابوالکلام صاحب اجازت دیں تو نام لکھا کرو(“مولوی ابوالکلام صاحب اجازت دیں” اس جملہ کے تیور اور اس کا پس منظر ملاحظہ کیجئے!ماہرؔ) ایسے مضامین گمنام ٹھیک نہیں،اس سے کیا فائدہ کہ ایک شخص کی زندگی گم ہوجائے،تمہاری قوت اور نمود سے بہرحال ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہوگا۔
شبلیؔ،اعظم گڑھ ۵۔اکتوبر۱۹۱۴ء
(آٹھواں خط،صفحہ نمبر ۱۸۰)ان خطوں کو خوب غور سے پڑھئے اور پھر مولانا آزاد کے اس جواب پر ایک نگاہ ڈالیئے جو “مدینہ” کے ایڈیٹر کے استفسار پر انھوں نے دیا ہے،اس کے بعد فیصلہ خود آپ ہی پر چھوڑتا ہوں،اپنی زبان سے کیا کہوں!اس خصوص میں اتنا عرض کردینا ضروری سمجھتا ہوں کہ “الہلال” میں بےنام کے مضامین جو چھپتے تھے ان کے بارے میں علامہ شبلیؔ مشتبہ ضرور تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مضمون نگاروں کا نام لکھا جائے تاکہ جس کی جو محنت اور کام ہے وہ اسی سے منسوب ہو،مولانا آزاد کے مزاج اور طبیعت کو بھی علامہ شبلیؔ نعمانی اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے،چنانچہ شبلیؔ نے جس مغالطہ سے لوگوں کو بچانے کے لئے عبدالسلامؔ ندوی کو خطوط لکھے تھے،اس مغالطہ میں لوگ مبتلا ہو کر رہے،اس مغالطہ کو خود مولانا ابوالکلام آزاد دور فرما سکتے تھے مگر انھوں نے اس کو اور پیچ در پیچ بنا دیا اور اس کو قہقہوں اور سگریٹ کے کشوں میں اڑا دیا۔
جزبہء فخر و ناز
میں نے جو کچھ اوپر لکھا ہے وہ نہ تو معاذاللہ “وحی و الہام” ہے اور نہ “حرفِ آخر” ہے کہ اس پر کسی قسم کا اضافہ و ترمیم ممکن ہی نہیں ہے،جو باتیں میری تحقیق میں آئیں،وہ میں نے بیان کردیں اور خدا جانتا ہے کہ میں نے کسی قسم کی تلبیس اور تحریف یا غلط بیانی سے کام نہیں لیا،کوئی صاحب میری غلطیوں پر مجھے مطلع فرما دیں اور میں مطمئن ہوجاؤں تو “فاران” ہی کے صفحات پر اس کا اعلان کروں گا اور اپنی غلطی اور تحقیق کی کمزوری کو مان لوں گا۔
مجھ تک اس تحقیق کے دوران جس قدر واقعات پہنچے ہیں،ان میں سے صرف چند واقعات میں ضبطِ تحریر میں لایا ہوں کہ اپنے اطمینان کی حد تک میں نے ان کو معتبر سمجھا،باقی بہت سی باتوں کو میں نے چھوڑ دیا۔۔۔۔۔۔مثلاً “تذکرہ” میں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اسلاف میں سے ایک بزرگ کو رفیع الدین سلامی کا شاگرد بتایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ (رفیع الدین سلامی) علامہ سخاوی کے شاگرد تھے اور اپنی کتاب “۔۔۔الامع فی اعیان قرن التاسع” میں سخاویؔ نے ان کا ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔۔مگر ادبی عربی کے ایک بہت بڑے عالم اور ماہر نے مجھ سے کہا کہ میں نے علامہ سخاویؔ کی اس کتاب کو بہت غور و خوض کے ساتھ پڑھا لیکن رفیعؔالدین سلامی کا نام مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔
جس نے بھی “تذکرہ” کو پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ “تذکرہ” انشاپردازی کے کمال کے علاوہ بہت سے تاریخی واقعات اور علمی مسائل کے حوالے کثرت کے ساتھ ملتے ہیں جو بلاشبہ مصنف کی وسعتِ مطالعہ پر دلالت کرتے ہیں،مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ میں “تذکرہ” کو اپنے حافظہ اور یادداشت کی بنا پر مرتب کررہا ہوں۔۔۔۔۔مگر مجھ سے ایک نہایت ثقہ شخص نے بیان کیا کہ “محی الدین صاحب قصوری(جن کو مولانا آزاد نے “عزیزی” لکھا ہے)نے خود مجھ سے کہا کہ آزادؔ جب رانچی میں نظر بند کر کے بھیجے گئے ہیں تو شروع شروع میں بےشک ان کے پاس کتابیں نہ تھیں مگر بعد میں ان کے پاس کتابیں بھیجوا دیں گئیں (کہنے والے کا مقصد غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن چند کتابوں کا مولانا آزاد نے “تذکرہ” نے ذکر فرمایا ہے،ان کے علاوہ دوسری کتابیں بھی فراہم کردی گئی تھیں۔ماہرؔ) اور “تذکرہ” کی تصنیف کے زمانے میں وہ کتابیں مولانا کے پاس موجود تھیں”
اس قسم کے بہت سے واقعات کا تذکرہ میں نے نہیں کیا کہ یہ صرف سماعی ہیں اور ان کی مزید تحقیق کے ذرائع مجھے میسر نہ آسکے۔۔۔۔۔۔۔۔سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں مولانا آزاد سے آخر ظہور میں کیوں آئیں!اس کا جواب میں نہ دوں گا کہ یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے،مسٹر ڈیسائی جنھوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے سوانح حیات لکھے ہیں جن کا اوپر ذکر آچکا ہے،انھوں نے جب مولانا آزاد کی خودنوشت “لائف”(تذکرہ) کو پڑھا اور مولانا کی زبانی ان کے حالات سنے تو مسٹر ڈیسائی کے قلم سے یہ جملے بےساختہ ٹپک پڑے:
(ترجمہ)
“کہا جاسکتا ہے کہ “فخرِ جائز” جو ایک شریف و اعلیٰ خانوادے اور علمی عظمت کی پیداوار ہے،مولانا صاحب کے خون میں دوڑ رہا ہے اور درحقیقت ایک حیثیت سے تو مولانا اپنے مفخر اسلاف پر بھی سبقت لے گئے۔۔۔۔۔۔”
مسٹر ڈیسائی،مولانا آزاد کا احترام کرتے تھے سیاسی میدان میں وہ ایک دوسرے کے ہم خیال اور رفیق کار تھے،اس لئے انہوں نے بڑے محتاط انداز میں
“Legitimate pride”
یعنی “فخرِ جائز” کہا ہے اوراس طرح ڈیسائی جی نے مولانا آزاد کے مزاج و طبیعت سے واقفیت اور نفسیات شناسی کا ثبوت دیا ہے،بس یہی “جزبہء فخر” ہے جو اپنے ظہور کے لیے طرح طرح کے کالبدا اختیار کرتا ہے جس کی چند جھلکیاں اوپر دکھائی جاچکی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔مولانا ابوالکلام آزاد کی ذات میں ایسی خوبیاں بلاشبہ موجود ہیں جن پر ان کا فخر کرنا بجا ہے مگر ان کے نیاز مندوں کو یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ اس “بابِ مفاخر” میں کچھ “افسانے” بھی شامل ہوگئے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کاش!۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایسا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نہ ہوتا! -
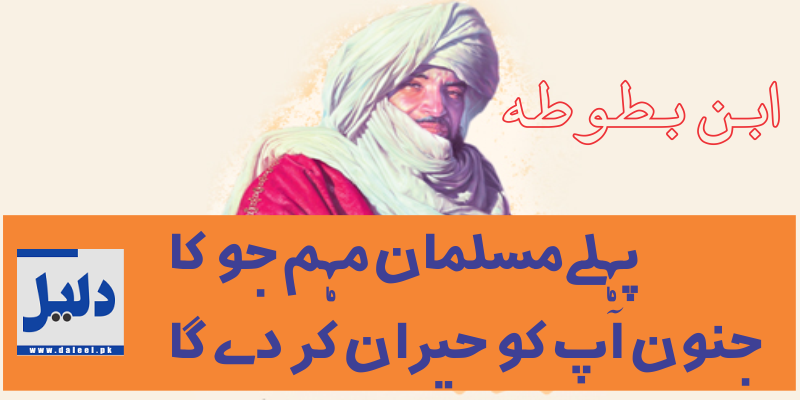
ابن بطوطہ-طارق عزیز خان

مراکش سے تعلق رکھنے والے مسلمان مؤرخ اور سیلانی ابن بطوطہ نے 1325 ء سے 1354ء کے دوران ایشیا، یورپ اور افریقا کی طویل سیاحت کی۔ تقریباً تین عشروں پر مشتمل ابن بطوطہ کے اس تاریخی سفر کی بدولت نہ صرف یورپی اقوام کو اسلامی ریاست کے جغرافیہ، تاریخ اور قوانین سے آگاہی حاصل ہوئی بلکہ دنیا کے الگ الگ خطوں میں بسنے والی اقوام کو ایک دوسرے کے حالات جاننے کا موقع بھی ملا۔
ابن بطوطہ کا اصل نام محمد بن عبداللہ ابن بطوطہ تھا۔ وہ 24 فروری 1304 ء میں مراکش کے شہر طنجہ (Tangiers) میں پیدا ہوا۔ اس نے شمالی مراکش کے ایک ’’سنی مالکی‘‘ مدرسے سے قرآن و حدیث، ادب، تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کی۔ اسے بچپن سے سیروسیاحت اور نئی نئی زبانیں سیکھنے کا شوق تھا۔ ابن بطوطہ نے 21 سال کی عمر میں اپنے والد اور چند قریبی لوگوں کے ساتھ سرزمین حجاز جانے کی منصوبہ بندی کی۔ اس زمانے میں خشکی کے راستے مراکش سے سعودی عرب کے پیدل سفر میں کل 16 ماہ لگتے تھے۔ تاہم ابن بطوطہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اگلے 24 سال تک اپنے وطن کو دوبارہ نہ دیکھ پائے گا۔ابن بطوطہ نے جون 1325 ء میں اونٹوں، خچروں اور گھوڑوں پر مشتمل ایک قافلے کے ساتھ مراکش سے اپنے تاریخی سفر کا آغاز کیا۔ وہ شمالی افریقا کے ساحلی علاقوں میں سفر کرتا ہوا تیونس پہنچا۔ وہاں دو ماہ گزارنے کے بعد وہ 1326 ء کے موسم بہار میں مصر اور فلسطین کے علاقوں پر مشتمل سلطنت مملوک (Mamluk Empire) کی حدود میں داخل ہو۱۔ مصر میں چند روزہ قیام کے دوران ابن بطوطہ نے تاریخی شہر اسکندریہ، غزہ اور قاہرہ کی سیاحت کی۔ اس نے سعودی عرب جانے کے لیے صحرائے سینائی (Sinai Desert)
کے مروجہ راستے کو اختیار کرنے کے بجائے بحیرہ احمر کے راستے جدہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم مصری ساحلوں پر مقامی باغیوں کی لوٹ مار کی وجہ سے اسے واپس قاہرہ آنا پڑا۔ وہ صحرائے سینائی کو پار کر کے ایشیا (فلسطین) میں داخل ہوا۔ ابن بطوطہ نے فلسطین میں مقدس مقامات کی سیاحت کی۔ اس نے ماہ رمضان، شام میں گزارنے کے بعد عربستان کا سفر اختیار کیا اور بالآخر اکتوبر 1326ء کے آغاز میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ میں چار دن قیام کے بعد حاجیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ ہوا۔ جہاں اس نے مناسک حج ادا کیے اور قریب ایک ماہ وہاں قیام کیا۔ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ابن بطوطہ نے مغربی ایشیا کی سیاحت کا فیصلہ کیا۔
17 نومبر 1326 ء کو ابن بطوطہ اپنے والد کو لے کر حاجیوں کے ایک قافلے کے ساتھ عراق روانہ ہوا۔ انھوں نے مدینہ منورہ میں مختصر قیام کیا اور نجد (Najd) کے علاقے میں داخل ہوئے۔ اگلے 44 دن کے دوران ان کے قافلے نے لگ بھگ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جزیرہ نما عرب کو پار کیا اور دریائے فرات کے کنارے آباد عراق کے شہر نجف میں داخل ہو گئے۔ وہ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا جنوب میں واقع بصرہ پہنچا۔ جہاں چند دن سیر سپاٹے کے بعد وہ ایران جانے والے قافلے سے وابستہ ہو گیا۔ یہ قافلہ مشرق کی طرف سفر کرتا ہوا جنوب مشرقی ایران میں واقع سلسلہ ہائے زاگروس (Zagros) میں داخل ہوا۔ مراکش کے خشک اور بنجر کوہ اٹلس میں زندگی گزارنے والے کسی افریقی باشندے کے لیے زاگروس کی برف پوش چوٹیوں کا نظارہ مبہوت کر دینے والا تھا۔ ابن بطوطہ نے فروری 1327 ء میں اصفہان (Esfahan) اور مارچ کے آغاز پر جنوبی ایران میں واقع شیراز کی سیاحت کی۔ وہ جون1327 ء میں ایک بار پھر عراق میں موجود تھا جہاں اس نے بغداد شہر میں 13 ویں صدی کے دوران چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان (Hulagu Khan) کے ہاتھوں ڈھائی جانے والی تباہی کا مشاہدہ کیا۔ مقامی لوگوں نے ابن بطوطہ کو بتایا کہ فتح کے نشے میں چور ہلاکو خان نے بغداد شہر کو آگ لگانے سے پہلے مقامی خلیفہ اور اس کے خاندان سمیت لگ بھگ 8 لاکھ عراقی باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بغداد کی سیر کے بعد ابن بطوطہ، شمالی ایران کے شہر تبریز اور مشرقی ترکی کے علاقوں کی سیاحت کے بعد وہ ایک بار پھر عراق پہنچا۔ جہاںوہ ایک قافلے سے وابستہ ہو کر 1329 ء میں دوبارہ مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ اس نے اپنے والد کے ساتھ دوسری بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔
مناسک حج ادا کرنے کے بعد ابن بطوطہ، یمن جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ بحیرہ عرب کی بندرگاہ عدن پہنچا۔ اس زمانے میں عدن کی بندرگاہ خلیج سویز، بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب کی طرف آنے والے تجارتی بحری جہازوں کا اہم پڑائو تھی۔ چونکہ اس وقت تک راس امید (Cape of Good Hope) کا بحری راستہ دریافت نہیں ہوا تھا۔ اس لیے گرم مسالوں کے یورپین اور عرب تاجر براستہ عدن، جنوبی ہندوستان کی بندرگاہ کالی کٹ جاتے تھے۔ ابن بطوطہ نے عدن کے بازاروں میں لونگ، دار چینی اور کالی مرچ کے ڈھیر لگے دیکھے۔ اس نے چند ہفتے یمن کی سیر کے بعد بحیرہ احمر کو پار کیا اور صومالیہ میں قدم رکھا۔ وہاں 1330 ء اور 1331 ء کے دوران صومالیہ، کینیا، تنزانیہ اور زین زی بار کے جزیرے کی سیاحت کی۔ وہ 1332ء میں ایک بار پھر مکہ معظمہ پہنچا، جہاں اس نے تیسرا حج ادا کیا۔
اس بار مکہ معظمہ میںقیام کے دوران ابن بطوطہ کی ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد بن تغلق سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مکہ معظمہ میں قیام کے دوران سلطان کے لیے مترجم کے فرائض سرانجام دیے۔ سلطان کی ہندوستان واپسی کے بعد ابن بطوطہ نے مراکش واپس جانے کے بجائے یورپ کی سیاحت کا فیصلہ کیا۔ پھر عراق اور شام میں مختصر قیام کے دوران اپنے والد کی خواہش پر اُنھیں دمشق ہی میں چھوڑ دیا۔ ابن بطوطہ 1333 ء میں ترکی اور جنوب مشرقی یورپ (یونان، بلغاریہ، یوگوسلاویہ اور جنوبی اٹلی) پر مشتمل بازنطینی سلطنت (Byzantine Empire) کی حدود میں داخل ہوا۔ اسی سال اس کی Constantinople (موجودہ نام استنبول) میں بازنطینی حکمران اینڈ رونی کوس سوم (Andronikos III) سے ملاقات ہوئی۔ اینڈ رونی سوم نے ابن بطوطہ سے مشرق وسطی کے سیاسی حالات معلوم کیے۔ استنبول کے بعد ابن بطوطہ کی اگلی منزل یوکرائن تھا۔ اس نے بحیرہ اسود (Black Sea) کو پار کیا اور یوکرائن کی بندرگاہ فیوڈوسیا (Feodosiya) میں قدم رکھا۔ وہ 1334 ء کے آخر میں دریائے وولگا پار کر کے بحیرہ کیسپین کے شمالی کنارے پر واقع روسی بندرگاہ استراخان (Aastrakhan) پہنچا۔ وہاں چند دن گزارنے کے بعد ابن بطوطہ، قازقستان سے ہوتا ہوا ازبکستان میں داخل ہوا جہاں اس نے بخارا اور سمر قند کے تاریخی شہروں کی سیاحت کی۔
1335 ء کے اواخر میں ابن بطوطہ، افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوا۔ وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا جنوبی پنجاب میں داخل ہوا۔ اس نے تاریخی شہر ملتان کی سیر کی اور صوبہ سندھ میں چند روز گزارنے کے بعد ہندوستان پہنچ گیا۔ اُس زمانے میں دہلی کے تخت پر مسلمان بادشاہ سلطان محمد بن تغلق براجمان تھا۔ سلطان کی ابن بطوطہ سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی، بادشاہ نے ابن بطوطہ کی بڑی آئو بھگت کی اور اسے قاضی کے عہدے پر سرفراز کیا۔ ابن بطوطہ نے اگلے دو سال تک ہندوستان میں نہایت شاہانہ زندگی بسر کی۔ اس دوران محمد بن تغلق نے اسے خلیج بنگال اور آبنائے ملاکا کے بحری راستے کے ذریعے ایک سفارتی مشن پر چین جانے کا حکم دیا۔ ابن بطوطہ نے جنوبی ہندوستان کی بندرگاہ کالی کٹ جانے سے پہلے گجرات کی سیاحت کی جہاں مقامی لیٹروں کے حملے میں وہ مرتے مرتے بچا۔ تقریباً ایک ماہ تک ساحل مالا بار پر بھٹکنے کے بعد وہ کالی کٹ پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ خلیج بنگال کے سفر کے دوران ابن بطوطہ کا بحری جہاز سمندری طوفان کے باعث مجبوراً انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا پہنچ گیا۔ اس نے سماٹرا میں چند ہفتے قیام کے دوان چین جانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وہ 1339ء کے آغاز پر ایک بار پھر جنوبی ہندوستان میں موجود تھا۔ چین کی ناکام سفارت سے خوف زدہ ابن بطوطہ نے اگلے چند ہفتے ایک مقامی مسلمان جمال الدین کی پناہ میں گزارے اور دہلی جانے کے بجائے مالدیپ کے جزائر پہنچ گیا۔ وہاں نو ماہ کے قیام کے دوران مقامی مسلمان حکمران عمر اول نے ابن بطوطہ کی علمیت سے متاثر ہو کر اسے اپنی ریاست کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ 1340 ء کے موسم بہار میں ابن بطوطہ نے مالدیپ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک نو مسلم خاتون سے شادی کی۔
ابن بطوطہ کی اگلی منزل سری لنکا تھی جہاں اس نے کوہ آدم (Adam’s Peak) کی سیاحت کی۔ سری لنکا میں مختصر قیام کے بعد اس نے اپنے ادھورے سفارتی مشن کی تکمیل کے لیے چین جانے کا قصد کیا اور اس بار کامیاب رہا۔ ابن بطوطہ 1342 ء میں سماٹرا، ویت نام اور فلپائن کی مختصر سیاحت کرتا ہواجنوبی چین میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں چین پر منگول سلطنت کے تابع یوآن (Yuan) خاندان کی حکومت تھی۔ ابن بطوطہ نے دریائے ینگسی (Yangzi) کے دہانے پر واقع چین کے سب سے بڑے شہر شنگھائی (Shanghai) میں چند دن گزارے۔ اس نے چین کے موجودہ دارالحکومت بیجنگ کے شمال میں واقع دیوار چین کو پار کیا اور منگول سلطنت کے دارالحکومت شانگ دو (Shangdu) پہنچا۔ پھر 1343 ء یا 1344 ء میں ابن بطوطہ مقامی منگول حکمران سے ملاقات کر کے اسے ہندوستان کے بادشاہ سلطان محمد بن تغلق کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ اس کام سے فراغت کے بعد ابن بطوطہ نے 1346 ء میں ہندوستان واپسی کا سفر اختیار کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ سلطان محمد بن تغلق کو چین کے حالات بتانے کے بعد شام میں مقیم اپنے والد کو ساتھ لے کر مراکش روانہ ہو جائے گا۔
ابن بطوطہ 1347 ء کے آغاز پر جنوبی ہندوستان پہنچا۔ اس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ محمد بن تغلق اپنے خلاف برپا ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا، ہندوستان سے روانہ ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بحیرہ عرب اور خلیج فارس سے ہوتا ہوا عراق اور پھر 1348 ء میں شام پہنچ گیا۔ دمشق میں اپنے والد کی تلاش کے دوران پتا چلا کہ اُن کا تو عرصہ پہلے (1333ئ) انتقال ہو گیا تھا۔ ابن بطوطہ نے مراکش واپسی سے پہلے مکہ معطمہ پہنچ کر چوتھی بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ حج کے فوراً بعد وہ افریقا جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو کر مصر، لیبیا اور الجزائر کی خاک چھانتا بالآخر 1349 ء میں مراکش واپس پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ نے لگ بھگ 24 سال بعد اپنے وطن طنجہ میں قدم رکھا۔ اسے یہ جان کر افسوس ہوا کہ چند ماہ پہلے اس کی والدہ بھی اس جہان سے کوچ کر چکی تھی۔ ابن بطوطہ کی بے چین طبیعت نے اسے چند روز بھی ٹک کر نہ بیٹھنے دیا۔ اس نے آبنائے جبل الطارق کو پار کر کے جنوبی اسپین میں واقع غرناطہ (Granada) کی اسلامی ریاست میں سیرو سیاحت کی۔ اسپین میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ 1350 ء میں دوبارہ طنجہ پہنچا۔ جہاں اس نے صحرائے اعظم (Sahara Desert) کو پار کر کے سلطنت آف مالی (Mali Empire) کے تاریخی شہر ٹمبکٹو (Timbuktu) تک رسائی مہم ترتیب دی۔شمالی افریقا میں 94 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا صحرائے اعظم دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے۔ آج (2011 ئ) اس عظیم ویرانے میں کل 25 لاکھ افراد رہتے ہیں جن کی اکثریت مصر، لیبیا، الجزائر، ماریطانیہ اور مالی سے تعلق رکھتی ہے۔ یوں تو شمالی افریقا کے باشندے زمانہ قدیم ہی سے صحرائے اعظم کی خاک چھانتے رہے ہیں، تاہم ابن بطوطہ کو وہ پہلا مہم جو مانا جاتا ہے جس نے ایک باقاعدہ مہم کے تحت اس کے مغربی حصے کو پار کیا۔ 1351 ء کی خزاں میں شمالی مراکش کے شہر فیس (Fes) سے ابن بطوطہ کے قافلے نے اپنے دلچسپ سفر کی شروعات کی۔ قریب تین سو کلومیٹر تک جنوب میں آگے بڑھنے کے بعد وہ لوگ مشرقی مراکش میںواقع سِجلماسا (Sijilmasa) کے تاریخی قصبے میں داخل ہوئے۔ (یاد رہے کہ مراکش میں واقع فیس اور سِجلماسا وہ تاریخی شہر ہیں جہاں بالترتیب 760 ء اور 790 ء میں پہلی اسلامی کالونی کی بنیاد رکھی گئی) سِجلماسامیں چار ماہ قیام کے دوران ابن بطوطہ کے قافلے نے اونٹوں اور خچروں کی خرید و فروخت کی۔ سِجلماساسے روانہ ہونے کے بعد ابن بطوطہ کا قافلہ مغربی الجزائر کے صحرائی علاقے میں داخل ہوا۔ جنوب میں ماریطانیہ کی طرف سفر کے دوران وہ لوگ دن کی جھلستی گرمی میں آرام کرتے اور رات میں نقطہ انجماد سے کم درجہ حرارت میں ٹھٹھرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کی کوشش کرتے۔ ابن بطوطہ کے قافلے نے جنوری 1352 ء کے دوران شمالی ماریطانیہ کے صحرائی علاقے الغزیب (El Gseib) کو پار کیا۔ اس کا قافلہ فروری کی شروعات میں مالی کے شمالی حصے میں واقع تغازا (Taghaza) پہنچا۔ عین خط سرطان پر واقع مالی کے اس حصے میں خشک نمکین جھیلوں کی بہتات ہے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ سلطنت مالی کی حدود میں شامل تھا اور یہاں ماسوفا (Masufa) قبائل آباد تھے۔تغازامیں قیام کے دوران ابن بطوطہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ نمک کی خشک جھیلوں سے اٹی اس سرزمین میں واقع مقامیوں کے گھر بھی نمک کی سلوں سے بنے ہوئے تھے۔تغازا میں دس روزہ قیام کے بعد ابن بطوطہ کا قافلہ تین سو کلومیٹر جنوب میں واقع ایک نخلستان (Bir al-Ksaib) پہنچا۔ یہاں سے انھوں نے پینے کے لیے پانی جمع کیا اور اپنے اونٹوں کو بھی جی بھر کر پلایا۔ ان کی اگلی منزل مالی کے جنوب حصے میں بہنے والا دریائے نائیجر تھا۔
لگ بھگ دو ماہ تک بے آب و گیاہ صحرا میں سفر کرنے کے بعد ابن بطوطہ، مئی 1353 ء میں دریائے نائیجر کے کنارے واقع مالی کے مشہور تاریخی شہر ٹمبکٹو پہنچا۔ اس نے اگلے چند ہفتے ٹمبکٹو کی سیاحت کی اور جولائی میں سلطنت مالی کے دارالحکومت بماکو (Bamako) میں داخل ہوا۔ جہاں اس کی مسلمان حکمران سلیمان مانسا سے ملاقات ہوئی۔ ابن بطوطہ نے پایا کہ مانسا ایک دولت مند حکمران تھا جس کے دربار میں موجود ہر شے سونے سے بنی تھی۔ مقامی لوگ مسلمان لیکن مذہب اور تہذیب سے کوسوں دور تھے۔ ان کی عورتیں لباس سے بے پروا معلوم ہوتی تھیں اور معاشرے میں جنسی بے راہ روی عام تھی۔ ابن بطوطہ اگلے آٹھ ماہ تک سلیمان مانسا کا مہمان بنا رہا۔ اس دوران بادشاہ نے اس کی دل بستگی کے لیے اپنی بیٹی سمیت عریاں کنیزیں تحفتاً پیش کیں جنھیں ابن بطوطہ نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ اکتوبر میں ابن بطوطہ نے وطن واپسی کا سفر کیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ مراکش واپس جانے والے اس کے قافلے میں 600 بے لباس لڑکیاں بھی شامل تھیں جنھیں فروخت کے لیے یورپ لے جایا جا رہا تھا۔
صحرائے اعظم کے تاریخی سفر کے بعد ابن بطوطہ نے 1354 ء کے آغاز میں مراکش واپس پہنچ کر مقامی حکمران سلطان ابو عنان فارس (Abu Inan Faris) سے ملاقات کی۔ اس نے سلطان کے سامنے اپنے 30 سالہ سفر سے متعلق مشاہدات بیان کیے اور اسے سلطنت مملوک، مغربی و وسطی ایشیا، یورپ کی بازنطینی سلطنت، ہندوستان اور چین کے حالات بتائے۔ ابن بطوطہ نے سلطان کو اپنے پاس موجود کاغذ کے ٹکڑوں، چمڑے کے تھیلوں، کپڑوں، لوہے کے برتنوں، جوتوں، سرپر پہنی پگڑی یہاں تک کہ اپنے جسم کے نمایاں حصوں پر بھی سفر سے متعلق لکھی تحریریں دکھائیں تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے ابن بطوطہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے طویل سفر نامے کو کتابی صورت میں شائع کرے۔ سلطان کی ہدایت پر ابن بطوطہ نے اس کے دربار میں موجود مؤرخ، شاعر اور قانون داں ابن جوزی الکلبی (Ibn Juzayy al-Kalbi) کو اپنے پاس موجود تحریری مواد اور ذہن میں موجود یادداشتوں کے سہارے اپنی طویل مہماتی داستان املا کروانی شروع کی۔
قریب ایک سال کی کڑی محنت اور تحقیق کے بعدابن جوزی نے ابن بطوطہ کے تاریخی سفر نامے کو مکمل کیا۔ مختلف ممالک کے تاریخی و جغرافیائی حالات پر مبنی اس کتاب کا نام ’’تحفتہ النظارفی غرائب الامصاروعجائب الاسفار‘‘ (A Gift to those who contemplate the wonders of cities and the Marvels of (Travellingہے۔ اس کتاب کو عربی میں مختصراً ’’الرحلہ‘‘ (The Rihla) اور انگریزی میں (The Journey) کہتے ہیں۔ اس سفر نامے کی اشاعت کے دوران ہی ابن بطوطہ کو مراکش کی سب سے بڑی عدالت کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس نے کوئی اور نئی مہم شروع نہیں کی یہاں تک کہ 1368 ء کے آخر یا پھر 1369 ء کے آغاز پرابنِ بطوطہ کا مراکش میں انتقال ہو گیا۔
بدقسمتی سے ابن بطوطہ کے تاریخی سفر نامے کی روداد اگلی چار صدیوں تک منظر عام سے غائب رہی۔ حتیٰ کہ اس دوران کسی مسلمان حکمران نے بھی اس نادر روز گار تاریخی دستاویز کو تلاش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یورپ میں 1800ء کے آغاز میں بعض عرب اسکالرز کی تحریروں کی بنیاد پر جرمن اور انگریزی زبان میں ابن بطوطہ کے تاریخی سفر سے متعلق اقتباسات شائع ہوئے۔ 1830ء میں فرانس کے الجزائر پر قبضے کے دوران فرانسیسیوں کو الجزیرہ شہر سے ابن بطوطہ کے اصل سفر نامے کے پانچ قدیم نسخے ملے۔ ان نسخوں کو فوری طور پر پیرس روانہ کر دیا گیا۔ جہاں فرنچ اسکالر Charles Defremery اور Beniamino Sanguinetti نے ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ انھوں نے تین سالہ تحقیق کے بعد ان نسخوں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا۔ جس کے بعد فرانس میں The Journey کی چار جلدوں پر مبنی پہلی کتاب شائع کی گئی۔ فرانس کے بعد پوری دنیا کی قابل ذکر زبانوں (غالباً اردو کے سوا) میں ابن بطوطہ کے تاریخی سفر نامے کے ترجمے شائع ہوئے۔ابن بطوطہ کا قدرتی موازنہ اطالوی مارکو پولو ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ان دونوں مہم جوئوں کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ دونوں ہی نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں مہمات کا آغاز کیا۔ مارکو پولو کے سفر کا بنیادی مقصد منگول حکمران قبلائی خان کو عیسائی یورپ کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام پہنچانا تھا جب کہ ابن بطوطہ کا طویل سفر محض اس کے شوق سیاحت کا آئینہ دار تھا۔ مارکوپولو کی یورپ واپسی کے بعد اس کے سفر نامے کی تفصیلات سرعت کے ساتھ یورپ کے طول و عرض میں پھیل گئیں۔ مارکوپولو کے برعکس ابن بطوطہ نے کہیں زیادہ علاقوں کی سیاحت کی۔ اس نے اپنی 30 سالہ مہم کے دوران ایشیا، یورپ اور افریقا کے لگ بھگ ایک کروڑ مربع کلومیٹر علاقے کی خاک چھانی اور تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر کا پیدل سفر طے کیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ کسی بھی سیلانی کی طرف سے طے کیا گیا آج تک کا سب سے طویل پیدل سفر ہے۔ ابن بطوطہ ایک زرخیز ذہن کا مالک، سیماب فطرت شخص تھا۔ اس پر ہر وقت اپنے قرب و جوار کے علاقوں کو دریافت کرنے کا جنون سوار رہتا تھا۔ اس کی بے چین طبیعت نے اسے کسی مخصوص علاقے تک محدود نہ رہنے دیا۔ نئی نئی دنیائوں تک رسائی کی جستجو نے اسے ہمیشہ حالت سفر ہی میں رکھا۔ وہ پہلا مسلمان مہم جو کہلایا جس نے اس زمانے تک دریافت شدہ تینوں براعظموں کی سیاحت کی تھی۔ گو کہ ابن بطوطہ نے اپنی مہمات کے دوران کسی نئے علاقے کو دریافت نہیں کیا، تاہم اس کی طویل سیروسیاحت کے نتیجے میں دنیا کے تین الگ الگ خطوں میں بسنے والی اقوام کو ایک دوسرے کے حالات جاننے کا موقع ملا۔
ہم ابن بطوطہ کے سفر نامے سے متعلق پائی جانے والی دو غلط فہمیوں کو دور کرتے چلیں۔ تاریخ سے ناواقف بعض ذرائع نے لکھا ہے کہ ابن بطوطہ اپنے سفر کے آخری مرحلے میں ایران پہنچا جہاں اس نے ایرانی بادشاہ ابو عنان فارس کے کہنے پر اپنے سفر نامے کو کتابی شکل دی۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ اس نے ایران کی سیاحت ضرور کی تھی،تاہم ایسے کوئی شواہد موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ابن بطوطہ کی کسی ایرانی بادشاہ سے ملاقات ہوئی ہو۔ شاید ابوعنان کے نام سے جڑے ’’فارس‘‘ کے لفظ سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ تھا۔ سچ یہ ہے کہ ابو عنان فارس، ایران کے بجائے مراکش کا سلطان تھا۔ وہ 1329 ء میں مراکش میں پیدا ہوا اور 1348ء اپنے والد ابوالحسن ابن اوتھان کی وفات کے بعد مراکش کا حکمران بنا۔ اسے 1358 ء میں قتل کر دیا گیا۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے سے متعلق دوسری غلط فہمی، ابن جوزی کے نام سے متعلق ہے۔ بعض ذرائع نے مشہور عراقی عالم، شاعر اور مؤرخ علامہ ابن جوزی کو ابن بطوطہ کے سفر نامے Rihla کا مصنف لکھا ہے۔ جب کہ سچ یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی، ابن بطوطہ کے دنیا میں آنے سے لگ بھگ سو سال پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ ان کا زمانہ 1116 ء سے 1206 ء کے درمیان ہے جب کہ ابن بطوطہ کے سفر نامے کے مصنف ابن جوزی الکلبی کا زمانہ 1321 ء سے 1357ء کے درمیان ہے۔
-

A Journey of Poster Boy – نصراللہ گورایہ
 یہ 19ستمبر 1994ء کا ایک خوبصورت دن تھا کہ مظفر وانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک سیرت اور پاکباز بیٹا عطا کیا۔ خاندانی روایات کے مطابق ساتویں دن بچے کا عقیقہ کیا گیا او برہان مظفر وانی نام رکھا گیا۔ اس وقت کہ جب نام تجویز کیا جا رہا تھا تو شاید یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ برہان واقعتا اللہ کی برہان بن کر رہے گا۔ مظفر وانی مقبوضہ کشمیر کے ڈسٹرکٹ پلوامہ اور ولیج ترال شریف آباد کے رہنے والے ہیں۔ ان کا تین منز لہ خوبصورت گھر اور گھر کے بالکل سامنے مسجد اور مسجد سے بلند ہونیوالی صدائیں وانی خاندان کو فوزو فلاح کی طرف بلاتیں اور یہ خاندان اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کھنچا چلا جاتا۔مظفر وانی مقامی ہائیر سکینڈری سکول کے پرنسپل ہیں اور ان کی اہلیہ بھی سائنس میں پوسٹ گریجوایٹ ہیں جب کہ وہ بھی مقامی سکول میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتی ہیں۔ مظفر وانی اور ان کی بیوی نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی اور برہانی وانی کے بڑے بھائی خالد وانی نے کامرس میں پوسٹ گریجوایشن کی۔
یہ 19ستمبر 1994ء کا ایک خوبصورت دن تھا کہ مظفر وانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک سیرت اور پاکباز بیٹا عطا کیا۔ خاندانی روایات کے مطابق ساتویں دن بچے کا عقیقہ کیا گیا او برہان مظفر وانی نام رکھا گیا۔ اس وقت کہ جب نام تجویز کیا جا رہا تھا تو شاید یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ برہان واقعتا اللہ کی برہان بن کر رہے گا۔ مظفر وانی مقبوضہ کشمیر کے ڈسٹرکٹ پلوامہ اور ولیج ترال شریف آباد کے رہنے والے ہیں۔ ان کا تین منز لہ خوبصورت گھر اور گھر کے بالکل سامنے مسجد اور مسجد سے بلند ہونیوالی صدائیں وانی خاندان کو فوزو فلاح کی طرف بلاتیں اور یہ خاندان اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کھنچا چلا جاتا۔مظفر وانی مقامی ہائیر سکینڈری سکول کے پرنسپل ہیں اور ان کی اہلیہ بھی سائنس میں پوسٹ گریجوایٹ ہیں جب کہ وہ بھی مقامی سکول میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتی ہیں۔ مظفر وانی اور ان کی بیوی نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی اور برہانی وانی کے بڑے بھائی خالد وانی نے کامرس میں پوسٹ گریجوایشن کی۔برہان وانی اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ پورے گائوں میں مشہور تھا۔ گلی محلے کے کسی بزرگ نے کوئی کام کہا تو برہان کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑے پہلے ان کی خدمت سرانجام دے ۔ برہان وانی اپنی اوائل عمری میں ہی مسجد جانے لگا اور دھیرے دھیرے مسجد کے ایک مستقل ممبر کی حیثیت اختیار کر لی۔اللہ تعالیٰ نے باطنی خوبصورتی کے ساتھ برہان کو جسمانی خوبصورت سے بھی خوب نوازا تھا۔ گہری کالی آنکھیں ، خوبصورت سیاہ بال، ستواں ناک 6فٹ قد اور سرخ و سفید رنگت کا مالک یہ نوجوان اپنے بارے میں کہتا ہے:
I am Burhan, I could have won the most beautiful man award of India, I chose to color my chest with blood and become a martyr for Azadi.
اپنی کلاس میں ہمیشہ نمایاں پوزیشن لینے ولا یہ نوجوان Cricket loving boy کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وریندر سہواگ اور شاہد آفریدی اس کے پسندیدہ کرکٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے دوست کہتے ہیں کہ وہ ایک بہترین بلے باز تھا اور اگر وہ فریڈم فائٹر کا راستہ اختیار نہ کرتا تو شاید دنیائے کرکٹ کا ایک چمکتا ہوا تارا ہوتا۔ بچپن سے لڑکپن کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے برہان وانی نے دیکھا کہ جگہ جگہ قابض انڈین فوج نے اپنے چیک پوسٹس قائم کی ہوئی ہیں اور عام لوگوں کو تنگ کرنا ایک روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ برہانی وانی کو بھی آتے جاتے بہت تنگ کیا جاتا لیکن ابھی تک تشدد کی نوبت نہ آئی تھی۔2010ء میں ایک دن برہان وانی اپنے بڑے بھائی خالد وانی کے ہمراہ پلوامہ سے واپس آ رہے تھے کہ واپسی پر قابض انڈین فوج نے انہیں روک لیا اور دونوں بھائیوں پر خوب تشدد کیا اور ان کو مجبور کیا کہ قریبی بستی میں جائو اور ہمارے لیے سگریٹ کے پیکٹس لے کر آئو۔ برہان وانی نے وعدہ کیا کہ آپ میرے بھائی پر تشدد نہ کریں تو میں آپ کو سگریٹ کے پیکٹس لا کر دیتا ہوں۔ برہان وانی سگریٹ لینے کے لیے چلا گیا لیکن جب وہ واپس پہنچا تو اس کا بھائی خالد وانی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا جس پر قابض انڈین فوج نے شدید تشدد کیا تھا۔ انڈین فوج کی وحشیانہ کاروائیوں کے بارے مظفر وانی کہتے ہیں۔ “Almost every one has been beaten up by Indian Army. You almost must have had your share.” ’’یعنی مقبوضہ وادی میں شاید ہی کوئی نوجوان یا بزرگ ایسا ہو جو قابض فوج کے بہیمانہ تشدد سے محفوظ رہا ہو وگرنہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور نازیبا سلوک روز مرہ کا معمول ہے۔‘‘یہاں سے برہان وانی کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔
2010ء میں یہ نواجوان اپنی زندگی کے پندرھویں سال میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایک’’ فریڈم فائٹر‘‘ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کا یہ موقف ہے کہ کشمیر کے مسئلہ کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نکا لاجائے وگرنہ ہم بھارت سے طاقت کے زور پر آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ پندرہ ، اٹھارہ سال کے اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ علم اور بصیرت سے بھی خوب نوازا تھا۔ جس کا اندازہ آپ مقبوضہ کشمیر میں ، کشمیری پنڈتوں کی علیحدہ کا لونیوں اور آباد کاری کے متعلق اس کے بیان سے ہوتا ہے ۔ میں جب اس کے اس بیان کو پڑھ رہاتھا تو مجھے اپنے ملک کی قیادت بہت بونی لگ رہی تھی اور برہان وانی کا خوبصورت چہرہ میرے سامنے تھا۔ آپ بھی اس کے الفاظ پڑھیں اور اس کی دور رس نگاہوں کو داد دیں۔”Israel-like situation would not be allowed in Kashmir”سادہ سا خوبصورت یہ جملہ اپنے اندر کتنی تاریخی حقیقتوںکو نمایا ں کر رہا ہے کہ جس سازش کو عالم عرب نہ سمجھ سکا ، اٹھارہ سال کا یہ نوجوان ان حقیقتوں کو بیان کر رہا ہے۔ یقینا اللہ تعالیٰ نے سچ فرما یا ہے کہ ’’کہ میں نے جسے حکمت (دانش مندی ) عطا فرمائی، اسے خیر کثیر سے نوازا‘‘
2010ء سے 2016چھ سال کا یہ مبارک سفر اس نوجوان نے جس عزیمت اور ہمت کے ساتھ گزارہ وہ تاریخ کاایک روشن اور سنہرا باب ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعنیات 6لاکھ بھا رتی فوج کو اس نوجوان نے نہ صرف تگنی کا ناچ نچایا بلکہ ایک ایٹمی صلاحیت رکھنے والی دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کا راگ الاپنے والی ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور مظفر وانی کے بقول بہت سارے انڈین فوجی اور High Profileکے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے اور طرح طرح کے لالچ اور ترغیبات کے ذریعے سے وہ برہان وانی کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے۔ایک انڈین اخبار کے مطابق “For the last two years, Wani had become an I-Con of military in the state of Jammu & Kashmir” اس نے ان چھ سالوں میں صدیوں کا سفر طے کیا اور بھارتی فوج اور حکومت کی طرف سے برہان وانی کے متعلق اطلاع دینے والے کے لیے 10لاکھ روپے کا انعام بھی مقرر کیا اور مقبوضہ وادی میں سوشل میڈیا کے استعمال کی بدولت اس نے اپنے افکار و نظریات کو خوب پھیلایا اور نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت اختیار کرتاچلا گیا۔اسی وجہ سے سوشل میڈیا میں اسے “Poster Boy”کے نام سے جانا جاتا ہے۔
13اپریل 2015ء کو برہان وانی کے بڑے بھائی خالد ان کے ایک دوست کے ساتھ برہان وانی کو ملنے کے لیے گئے لیکن قابض انڈین فوج نے خالد وانی اور ان کے دوست کو شہید کر دیا۔برہان وانی پورے بھارت کی سرکار کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا اور ایک رومانوی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہاتھا۔ ان چھ سالوں میں اس نے بیسیوں ایسے معرکے سر انجام دیے کہ بھارتی فوج ہر دفعہ سٹپٹا کر رہ جاتی۔ انڈین فوج اور بھارتی سرکار کی بہت ساری اعلیٰ سطحی اجلاس میں برہان وانی کے تذکرے ہونے لگے۔ لہذا انڈین فوج نے ایک ’’اسپیشل آپریشن گروپ‘‘ قائم کیا اور اعلیٰ سطح کی Intelligence Sharingکی گئی۔ اور بالآخر آٹھ جولائی 2016ء کو بندورہ گائوں کے قریب انڈین فوج کے ساتھ ایک معرکے میں برہان وانی نے جام شہادت نوش کیا۔ پورے بھارتی میڈیا میں برہان وانی کی شہادت کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا گیا۔ اور انڈین فوج نے اسے ایک بہت بڑی فتح سے تعبیر کیا۔ تقریباً کم و بیش تمام اخبارات میں برہان کی شہادت کو شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا گیا۔برہان وانی کو پاکستان پرچم میں لپیٹ کر 21گنوں کی سلامی دی گئی اور اپنے ہی آبائی گائوں ترال میں اپنے بڑے بھائی خالد وانی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔برہان وانی کے جنازے کا منظر بھی بہت دیدنی اور تاریخی تھا۔ دنیا بھر میں 50سے زائد مقامات پر برہان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا۔برہان وانی کی شہادت کے بعد بھارتی میڈیا اور حکومت کے تجزیے اور تبصرے اس کو ایک بہت بڑی کامیابی بنا کر پیش کر رہے تھے لیکن ان کے علم میں نہ تھا کہ
گرا ہے جس بھی خاک پر قیامتیں اٹھائے گا یہ سرخ سرخ گرم گرم تازہ نوجواں لہو!برہان وانی کی شہادت نے مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کو ایک نیا موڑ دیا اور تقریباً 100دن مکمل ہونے والے ہیں کہ آئے دن تحریک آزادی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور بھارت اپنی تمام تر قوت کے بل بوتے پر اس کو روکنے ہیں ناکام رہا ہے اور دنیا کے ہر محاذ پر اس کو ھزیمت اٹھانا پڑھ رہی ہے۔کشمیر کے لوگوں نے تو یقینا اپنا حق ادا کر دیا اور سرخرو ٹھہر کے لیکن کیا اسلام آبادکے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سیاسی پنڈت بھی اپنا کردار ادا کرتے تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ آج بہت مختلف ہوئی۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ بھارت سفارتی سطح پر اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریگا۔لیکن ان شاء اللہ ناکام و نامراد ٹھہرے گا کیو نکہ بہت سارے برہان وانی اب اس مشن کو بڑہانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور پورا کشمیر، ’’کشمیر بنے گا پاکستان‘‘ کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ لیکن اے کاش ! اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی سید علی گیلانی عطار کرتے کہ جس نے اپنی پوری زندگی جس ہمت ہمت او استقامت کے ساتھ گزاری ہے وہ قابل دیدنی ہی نہیں قابل تقلید بھی ہے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جیل میں گزارنے والا یہ نوجوان بوڑھا پکار پکار کر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے لیکن اے کاش کہ گہری نیند سوئے ہوئے ہر حکمران علی گیلانی اور کشمیریوں کی سرگو شیوں کو سن سکیں۔
اک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانوں سے اٹھا
آنکھ حیراں ہے کہ کیسا شخص زمانے سے اٹھا -
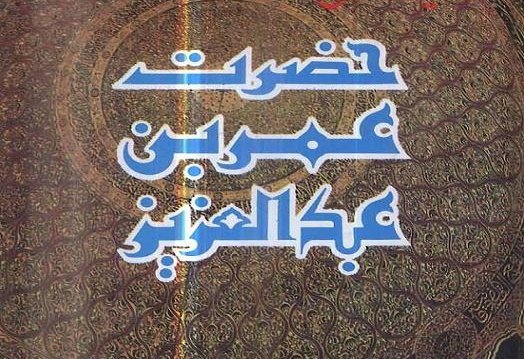
ہمارا جمہوری نظام اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز – سید وجاہت
جب اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے وزیر رجاء بن حیوہ سے مشورہ طلب کیا کہ میں اپنا جانشین کس کو بناوں ، خلفاء بنو امیہ کی روش تو یہ رہی ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کے لئے ہی وصیت کرجاتے تھے اور ان کے وزاء بھی انہیں اسی قسم کا مشورہ دیتے تھے لیکن رجاء بن حیوہ ایک جلیل القدر تابعی تھے، آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے علم حاصل کیا ، یہی وجہ ہے کہ رجاء بن حیوہ نے عام روش کے مطابق سلیمان بن عبد الملک کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ وہ اپنے بیٹے ہشام کو خلیفہ بنائے بلکہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز جیسے نیکوکار اور مخلص قیادت کے انتخاب کا مشورہ دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے استاذ صالح بن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں ، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو” کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد میں خاندان بنوامیہ ، وزراء کی موجودگی میں سلیمان بن عبدالملک کی وصیت سنائی گئی تو دو لوگوں کی زبان پر اناللہ وانا الیہ راجعون کے الفاظ تھے، ایک ہشام بن سلیمان کی زبان پر کہ وہ خلافت سے محروم ہوگیا تھا اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زباں پر جو اس خلافت کو بار عظیم سمجھ رہے تھے جو کسی بھی طرح سے اس خلافت کی ذمے داری اٹھانے کے لئے تیار نہ تھے ، جب حضرت نے اپنے خلیفہ بنائے جانے کا اعلان سنا تو حضرت نے یہ الفاظ کہے:
لوگو ! میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے اس لیے میری بیعت کا جو طوق تمہاری گردن میں ہے خود اسے
اتارے دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔
یہ الفاظ سننے تھے کہ خاندان بنوامیہ سمیت تمام لوگوں نے بلند آواز سے کہا ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہوگئے۔ پھر زمین و فلک نے وہ نظارا بھی دیکھا کہ دو ڈھائی سال کے عرصے میں اس مرد قلندر نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنادیا ، دنیا کو عمر الفاروق کی یاد دلا دی، معلوم ہوا کہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ حکومت کی آرزو نہیں کرتے بلکہ وہ ڈرتے ہیں اس بار عظیم کو اٹھانے سے ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے عہدہ طلب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم
یہ عہدے منصب انہیں نہیں دیتے جو ان کے طلب گار ہوں.دوسری بات یہ کہ آج دنیا عمر بن عبدالعزیز کو تو جانتی ہے لیکن رجاء بن حیوہ جن کے مشورے کے بنیاد پر ہی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو منتخب کیا تھا، آج ان کے نام اور کام سے صرف اہل علم ہی واقف ہیں عوام واقف نہیں، تاریخ پڑھیں تو ایسے بہت سے کارنامے ہیں جن کا سہرا ایسے لوگوں کے سر ہے کہ جن کے نام سے ہی دنیا واقف نہیں تو کیا ہمارے ناواقف ہونے سے اللہ ان کے اجر کو کم کردے گا؟ یقینا جس قدر امیر المومنین رحمہ اللہ اجر کے مستحق ہوں گے اسی قدر رجاء بن حیوہ کو بھی اجر ملے گا ، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ ، کیونکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود نیکی کی ہو۔
یہاں ہمارے لیےایک سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ انسان اگر صحیح لوگوں سے مشاورت کی عادت ڈالے تو ایسا شخص کبھی بھی نامراد و ناکام نہیں ہوسکتا ، ہماری ناکامیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مشاورت کے بغیر یا نااہل لوگوں کی مشاورت سے کام کرتے ہیں ، ہمارے ملک میں جمہوری نظام ہے اس جمہوری نظام کی یہی سب سے بڑی
خرابی ہے کہ حکومت کے بھوکے لوگ اقتدار کو حاصل کرنے کے لئے سر دھڑ کی بازی لگادیتے ہیں ، پیسہ پانی کی طرح پہایا جاتا ہے ، اب ظاہر ہے اس قدر محنت و کوشش کے بعد لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ خرچ کرکے اقتدار کو حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی عوام کی حقیقی معنوں میں خدمت کرسکتا ہے؟ہم بھی بدقسمت قوم ہیں کہ ہم نےیہ جمہوری نظام غیروں سے متاثر ہوکر اپنایا لیکن وہ اصول و ضوابط فراموش کردیئے جن کی بناء پر یہ نظام موثر ہوسکتا تھا، جمہوریت انہیں معاشرے میں کامیاب ہوسکتی ہے، جہاں شرح خواندگی مناسب حد تک موجود ہو ، جہاں کے معاشرے کے افراد منشور دیکھ کر سیاسی پارٹیوں کے اہداف کا تعین کرسکیں، جن میں موازنہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو ، بدقسمتی سے ہمارے یہاں قومیت، لسانیت، ڈھول کی ڈھاپ ، لنگر و دعوت کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ کرنے کا رواج ہے ، یہاں شرح خواندگی افسوس ناک حدتک کم ہے ، پارٹی منشور دیکھ کر موازنہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ، یہی روش رہی تو اگلے پچاس سال بعد بھی تبدیلی نہیں آسکتی، مخصوص خاندان ، مخصوص برادریاں اور ان کی آل و اولاد ہی ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے گے، کیونکہ ہمارا نظام ہی ایسا ہے کہ مخلص دیانت دار ، پڑھے لکھے لوگ ایوان اقتدار تک اپنی مدد آپ کے تحت نہیں جاسکتے ۔
-

علامہ عنایت اللہ مشرقی، ایک جینئس جسے قوم نے بھلا دیا – ثناءاللہ احسن
لاہور کےاچھرہ کی تنگ گلیوں سے گزر کر جب آپ ذیلدار روڈ پر پہنچیں گے تو ایک الگ تھلگ سیمنٹ کے پلاسٹ والا پرانا مکان نظر آئے گا۔ زنگ آلود گیٹ کھول کر اندر جائیں تو اب بھی ایک لکڑے کے بوسیدہ شوکیس میں آپ کو 1942 کی رینالٹ بینز کا ڈھانچہ نظر آئے گا۔ اس زنگ آلود گلتی سڑتی کار کے بالکل ساتھ ہی دو قبریں بھی ہیں. ایک علامہ عنایت اللہ مشرقی کی اور دوسری ان کی شریک حیات کی۔ یہ کار ایڈولف ہٹلر نے علامہ صاحب کو بطور تحفہ پیش کی تھی۔ ب1942 ماڈل کی رینالٹ بینز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب نازی فوجوں نے فرانس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے بہت محدود تعداد میں مرسیڈیز بینز کا اسپیشل ایڈیشن تیار کیا تھا۔ کیونکہ اس کو رینالٹ کی فیکٹری میں تیار کیا گیا تھا اس لئے اس کو رینالٹ بینز کا نام دیا گیا۔ اس لہز سے اس کار کی تاریخی اہمیت اور قدرو قیمت کا اندازہ لگا لیجیے جس کا ہماری کسی حکومت نے قدر نہیں کی اور نہ اس نایاب ورثے کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا گیا۔ تصاویر میں آپ نئی رینالٹ اور اس کی موجودہ حالت زار دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ مشرقی ایک ایسا جینئس تھا کہ جس کے نام اور کام کو ہماری درسی کتب میں ہونا چاہئے لیکن ہمارے اصل ہیروز کو کوئی نہیں جانتا کہ سچ مچ بھینس کو بھلا بین کی کیا سمجھ۔
خود ہٹلر کے پاس چھ رینالٹ بینز موجود تھیں جبکہ اس نے جنرل رومیل سمیت ڈیڑھ سو افراد کو یہ کاریں بطور تحفہ پیش کی تھیں جن میں سے ایک علامہ مشرقی بھی تھے۔ علامہ کی سائنسی سوجھ بوجھ اور ماہر ریاضیات کی حیثیت سے ان کی خدمات کے اعتراف میں یہ کار پیش کی گئی۔ ان کو انڈیا کے بہترین دماغ کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ 1970 میں بینز کمپنی نے علامہ کی فیملی کو اس کار کے بدلے پانچ لاکھ ڈالر کی پیشکش کی تھی جو علامہ صاحب کی فیملی نے رد کردی۔ اب نئی نسل کو اس بیش قیمت ورثہ کے باعے میں کچھ خبر نہیں کہ یہ کیا حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کار آج بھی اپنی اور اپنے مالک کی بے توقیری پر نوحہ کناں ہے۔ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا فرض بنتا ہے کہ اس کار کو قومی و تاریخی ورثہ قرار دے کر اس کی مرمت و رنگ و روغن کروا کر اس کو کسی میوزیم میں محفوظ کیا جائے ورنہ کچھ عرصہ بعد یہ صرف ایک کاٹھ کباڑ کا ڈھیر رہ جائے گی۔ صحافی حضرات اس کی طرف توجہ دیں اور حکومت کی توجہ اس کی جانب مبذول کروائیں۔
اسی لاہور میں وہ عظیم المرتبت شخص علامہ مشرقی رہتا تھا جسکے بارے میں آئن سٹائن نے کہا کہ یہ ایک جینئس ہے…کہا جاتا ہے کہ علامہ مشرقی نے حساب کا ایک
سوال جو آئن سٹائن کو بھی پریشان کرتا تھا، ایک ڈبیہ پر حل کر دیا تھا… اڈولف ہٹلر بھی اس کی شخصیت سے اتنا متاثر ہواکہ اسے ذاتی طور پر ایک سیاہ ڈیملر لموزین تحفے میں دی اور یہ کار ابھی تک اچھرے میں ایک چھت سے معلق ہے…علامہ مشرقی کی جدوجہد آزادی کی کہانی ہمارے کسی نصاب میں شامل نہیں…تین سو تیرہ خاکسار… جنگ بدرکی یادگار…جب لاہور کے اندربٹی گلی میں پورے انگریز سامراج سے ٹکرائے تھے اس کا ہمارے نصابوں میں کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں‘ صرف تحریک گور کنان کے قصے ہیں‘ ہماری آج کی نسل نہ بھگت سنگھ کی قربانیوں سے واقف ہے اور نہ ہی علامہ مشرقی کی جرأت اور ولولے اور جینئس سے آگاہ ہے…اس لئے کہ …جو کچھ بھی ظہور پذیر ہو جائے اس کا ریکارڈ آئندہ نسلوں تک منتقل نہ کیاجائے تو گویا کچھ بھی ظہور پذیر نہ ہوا تھا۔فورڈ کے کہنے کے مطابق تاریخ واقعی ایک بینک ہے۔• عالم اسلام کے فرزند….جنہوں نے دنیا کی قوموں کو اجتماعی موت و حیات کے متعلق پیغام اخیر اور تسخیر کائنات کا پروگرام اپنی شہرہ آفاق کتاب” تذکرہ“ (1924) کے ذریعے دیاتو دنیا بھر کے عالم دنگ رہ گئے۔ جس پر 1925ء میں مشروط طور پر ادب کا ”نوبل پرائز“ پیش ہوا کہ اردو ہماری تسلیم شدہ زبان نہیں، کسی یورپی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے مگر شہرت و دولت سے بے نیاز مصنف نے لینے سے انکار کر دیا۔
بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ برسوں پہلے 1924ءمیں علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب کو 36سال کی عمر میں اپنی کتاب ” تذکرہ ” پر نوبل پرائز کے لئے نامزد کیا گیا تھا – لیکن نوبل کمیٹی نے شرط یہ رکھی تھی کہ علامہ صاحب اس کتاب کا کسی یورپی زبان میں ترجمہ کروائیں مگر علامہ مشرقی نے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح وہ نوبل پرائز نہ حاصل کر سکے – تذکرہ کتاب میں علامہ صاحب نے قران اور قدرت کے قوانین کا سائنسی تجزیہ کیا ہے – اس کتاب کا ترجمہ نہ کروانے کی ان کی کیا توجیح ہو گی یہ سمجھ نہیں آتی – کیونکہ وہ نہ صرف روایتی ملا نہ تھے بلکہ ان کے بہت خلاف تھے۔
دنیا کے بیس ہزار سائنسدانوں کو ”انسانی مسئلہ“ کے عنوان سے خط لکھ کر دنیاوی ترقی کو بے جان مشینوں کے چنگل سے نکال کر کائنات کو مسخر کرنے ، انسانی زندگی اور اس کی روح کو کنٹرول کرنے اور دیگر کروں میں زندگی کی موجودگی کے آثار کے راز ازروئے قرآن افشاں کر دئیےجس کا ہماری کسی نصابی کتب میں ذکر تک نہیں۔ صد افسوس!!!!
علامہ عنایت مشرقی صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے – ایک بہت بڑے ریاضی دان کے علاوہ وہ سیاسی ، سماجی اور مذہبی سکالر بھی تھے – انگلستان میں اپنی تعلیم کے دوران کیمبرج یونیورسٹی میں ان کی دوستی سر جین جونز اور سر نیوٹن جیسے بڑے سائنسدانوں سے ہوئی – جنہیں علامہ صاحب نے اسلام اور اپنے پیغمبر صلعم کے بارے
میں آگاہ کیا – اور شنید ہے انہوں نے اسلامی کتب کے مطالعہ کے بعد علامہ صاحب سے جنگ کے دوران قید ہونے والی خواتین سے سلوک پر سوال اٹھایا – جس پر علامہ بہت پریشان ہوے اور کچھ عرصہ تعلیمی سلسلے کو منقطع کر کے قران اور حدیث کے مطالعہ میں اپنے آپ کو غرق کر لیا – اس کے بعد ہی انہوں نے تذکرہ اور ملا کا غلط مذہب نامی کتب لکھیں – اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حدیثوں میں جنگی قیدی خواتین سے جس سلوک کا ذکر ملتا ہے کہ انہیں اپنی مرضی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. قران میں ایسے سلوک کا enayatذکر ہر گز نہیں ہے – اللہ نے تو صاف کہا ہے کہ قیدی خواتین کو جزیہ لے کر دشمنوں کے حوالے کر دیں – اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکاری ہوں تو صلح رحمی کرتے ہوے بغیر جزیہ کے دشمن کو ان کی خواتین واپس کر دیں ۔ ہمارے سیدی مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں حدیث والے ورژن کو ہی مستند لکھا ہے اور اس سلوک کی انتہائی بھیانک شکل کا مظاہرہ آجکل داعش کے جنگی جنونی کر رہے ہیں۔علامہ مشرقی صاحب صرف 25سال کی عمر میں کالج پرنسپل بن گئے تھے اور 29 سال کی عمر میں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے انڈر سیکریٹری بن گے تھے – بعد میں انہیں کئی بڑے عہدے آفر ہوے جیسے افغانستان کی سفارت مگر انہوں نے ایسی کسی آفر کو قبول نہیں کیا بلکہ سرکاری ملازمت چھوڑ کر 1930ءمیں خاکسار تحریک کی داغ بیل ڈالی – اس تحریک کا بنیادی مقصد غریب عوام کی بلاتفریق مذہب و فرقہ خدمت کرنا تھا – اس تحریک کیلئے کئی دفعہ وہ جیل بھی گئے۔ وہ انڈیا کی تقسیم کے حق میں نہیں تھے اور اسے انگریزوں کی سازش قرار دیتے تھے – علامہ مشرقی نے 1956ءمیں منٹو پارک میں پیش گوئی کی تھی کہ اگر مشرقی پاکستان کے مسائل کو حل نہ کیا گیا تو یہ علیحدہ ہو جائے گا اور ان کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔
• پاکستان کے وہ رہنما….جن کی نماز جنازہ میں دس لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کر کے ان کے عمل و کردارکی صداقت پر اپنی مہرثبت کی۔ • پاکستان کے پہلے رہنما ….جن کو بعد از مرگ حضوری باغ (بادشاہی مسجد لاہور) کے وسیع و عریض مقام پر قائدین خاکسار تحریک کوحکومت کی جانب سے تدفین کی پیش کش کی گئی تو انہوں نے اپنے عظیم المرتبت قائد کی وصیت منظر عام پر لاکر امت مسلمہ اور ملت پاکستانیہ کو حیرت زدہ کر دیا کہ”مرحوم کی تدفین، ان کی اپنی زرخرید زمین ذیلدار روڈ، اچھرہ لاہور میں ہو اور اس پر گھنٹہ گھر تعمیر کر کے تحریر کیا جائے کہ ”جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی تباہ ہو جاتی ہے“ ۔ جہاں پر چھولداری میں بیٹھ کرآپ نے ”خاکسارتحریک“ کو عا لمگیر سطح پر چلایا اور اسی مقام پر ہی پیوند خاک ہوکر اپنی خودداری ثابت کر دی۔
• مقام غور و فکر ہے کہ ایسی عظیم المرتبت شخصیت کے ساتھ ۱۹۴۷ءسے لے کر اب تک حکمرانوں ، ارباب تعلیم و صحافت، تاریخ نویسوں، کالم نگاروں، محققوں، قومی رہنماﺅں اور الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کا متعصبانہ رویہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر نوجوان نسل سے انہیں کیوں بے خبر رکھا جا رہا ہے؟ جس کا واضح ثبوت یہی ہے کہ ابھی تک ”باقیات فرنگی سامراج“ کاخاتمہ نہیں ہو سکا؟ جو ہم سب کےلئے لمحہ فکریہ ہے!