جدید سیاسی اسلام تقریباً ایک صدی قبل مصر میں سامنے آیا اور اب یہ مسلم دنیا کو نئے سرے سے مرتب کررہا ہے۔ اسلام اِزم کا نام پانے والے اس مضبوط نظریے کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ ایک ارب سے زائد مسلمانوں کی آزادی اور عظمت کا دار و مدار ریاست کی جانب سے شریعت نافذ کیے جانے پر ہے، جیسا کہ اسلامی تاریخ کے اکثر ادوار میں ہوتا رہا ہے۔ اسلام پسندوں کی محاذ آرائی شریعت کو مسترد کرنے والے مسلمانوں اور اُنہیں اس استرداد پر اکسانے والے غیر مسلموں کے ساتھ ہے۔ کبھی معتدل اور کبھی متشدد ہوتی اس محاذ آرائی کے بطن سے ۱۹۵۲ء میں مصر اور ۱۹۷۹ء میں ایران کے انقلاب نے جنم لیا، اور ۲۰۰۱ء میں القاعدہ کے حملوں، ۲۰۱۱ء کی عرب بہار اور خود کو اسلامی ریاست کہلانے والی داعش جیسی شدت پسند تنظیموں کے ابھرنے کا سبب بھی یہی ہے۔
مسلمانوں میں اس تفریق کا سبب اسلام نہیں ہے۔ اصل مسئلہ مسلمانوں کے درمیان پایا جانے والا یہ اختلاف ہے کہ مذہب کو معاشرتی قوانین اور اداروں کی تشکیل میں کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ زیادہ تر مسلمان، چاہے وہ شدت پسند ہوں یا نہ ہوں بہرحال جہادی یا انقلابی نہیں ہیں۔ لیکن بہتر عوامی نظام کے حوالے سے جاری کشمکش نے انہیں منتشر کرکے ایسی مخاصمتوں میں ڈال دیا ہے جو سمجھوتا نہیں ہونے دیتیں۔ نتیجہ مسائل کی نہ سلجھنے والی ایک ایسی گُتھی کی صورت میں نکلا ہے جس میں ہر ایک، دوسروں کو الجھا رہا ہے۔
مغربی دانشور اور پالیسی ساز ایک عرصے سے اس تنازع کو سمجھنے کی کوشش میں ہیں لیکن اب تک انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ اسلامی فلسفۂ قانون، الٰہیات اور تاریخ کے ماہرین نے سیاسی اسلام پر بلاشبہ بہت کام کیا مگر وہ اسے ایک انوکھی چیز ہی سمجھتے رہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ اسلام اِزم محض اسلامی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ’’ازم‘‘ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ عوامی زندگی کو ترتیب دینے والا ایسا نظریہ اور لائحۂ عمل ہے جس کا دیگر نظریات کی طرح تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ مغرب سے زیادہ نظریات دنیا کے کسی خطے نے پیدا نہیں کیے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ آج کے مشرقِ وسطیٰ کو سمجھنے کے لیے مغرب اپنی نظریاتی کشمکش کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لے۔
درحقیقت آج مسلم دنیا کے کچھ حصے ۴۵۰ برس قبل کے مذہبی جنگوں میں گِھرے شمال مغربی یورپ سے پُراَسرار مماثلت رکھتے ہیں۔ آج کی طرح اُس وقت بھی مذہبی سرکشی کی لہر نے ایک بڑے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا اور مختلف ممالک کو تباہ کرتی ہوئی بہت سے دیگر ملکوں کو ٹوٹ پھوٹ کے خطرات سے دوچار کرگئی۔ صرف ۱۵۶۰ء کی دہائی میں فرانس، نیدرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کو پروٹسٹنٹ فرقے کی ایک شاخ کیلوِن اِزم (Calvinism) کے ماننے والوں کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کیلون ازم اکیسویں تو کجا انیسویں صدی کے پریسبائی ٹیرئین (Presbyterian) لوگوں جیسا بھی نہیں تھا۔ کیتھولسزم (Catholicism)، لُوتھرینزم (Lutheranism) اور دیگر عیسائی نظریات کی طرح جدید ابتدائی کیلون ازم بھی محض مذہبی احکامات کا مجموعہ نہ تھا بلکہ ایک مکمل سیاسی نظریہ بھی تھا۔ اس نظریے کا ارتقا ایسے وقت میں ہوا جب یورپ کا سماجی معاشی نظام کسی حد تک رومن کیتھولِک کلیسا نے اپنے ہی اصولوں پر استوار کیا تھا، اور کیلون اِزم نے اسی کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اُن دنوں کسی نظریے کو اپنانے کا مطلب مذہبی کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر وابستہ ہونا بھی تھا لہٰذا مذہبی جنگیں بلاشبہ سیاسی جنگیں بھی تھیں۔
یہ بغاوتیں ریاست کو کسی ایک مسیحی فرقے کی سرپرستی پر مجبور کرنے کے لیے جاری ۱۵۰ سالہ کشمکش کا حصہ تھیں اور آج بھی یہی کچھ ہورہا ہے۔ نظریاتی پیشواؤں نے اثر و رسوخ بڑھانا چاہا، مخالفت کو بے دردی سے کچلا گیا، وقتاً فوقتاً مذہب کے نام پر قتلِ عام کیا گیا اور بیرونی قوتیں کسی نہ کسی دھڑے کی حمایت کرتے ہوئے جھگڑے میں کود پڑیں۔ یہ طوائف الملوکی بالآخر دردناک تیس سالہ جنگ پر منتج ہوئی جس کے دوران مقدس رومی سلطنت (Holy Roman Empire) کا مرکز کہلانے والے جرمنی کی کم از کم ایک چوتھائی آبادی فنا ہوگئی اور جب یہ بحران ختم ہوا تو دو اور نظریاتی جنگیں شروع ہوگئیں: ایک اٹھارہویں صدی میں بادشاہت اور آئینی بالادستی کے درمیان اور دوسری بیسویں صدی میں لبرل ازم اور کمیونزم کے مابین۔
نظریاتی کشمکش کے ان تین ادوار میں مغربی ممالک معاشرتی نظم کی خاطر منقسم رہے اور یہی ادوار آج ہمیں بہترین سبق دیتے ہیں۔ عمومی نظر سے دیکھا جائے تو مغربی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں بالادستی کا حالیہ بحران نہ تو اپنی شدت میں بے نظیر ہے اور نہ ہی اس کے سیدھے سادے طریقے سے حل ہونے کا کوئی امکان ہے۔ ماضی کے باعظمت نظریات کی طرح سیاسی اسلام نے بھی علاقائی تنازع کو ہوا دے کر اس سے تقویت حاصل کرلی ہے اور اب مستحکم ہے۔ مشرقِ وسطیٰ کو جس طرح کی نظریاتی مسابقت کا سامنا ہے، اس میں سب کی جیت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ ایسے نظریے یا تو مخالف نظریات کو نشوونما دیتے ہیں یا پھر انہیں اپنے اندر جذب کرلیتے ہیں۔ ایسا عموماً تبھی ہوتا ہے جب تنازع اپنے اندر بیرونی طاقتوں کو گھسیٹ لیتا ہے اور علاقائی نظم از سرِ نو مرتب ہوتا ہے۔ یہ اسباق مشرقِ وسطیٰ کو درپیش حالیہ چیلنجوں سے نمٹنے کا نسخہ تو نہیں بتاتے لیکن اتنا اشارہ ضرور دیتے ہیں کہ خطے کو لاحق عوارض نئے نہیں ہیں اور ریاستیں اور ان کے رہنما تشدد کو کم کرنے اور انسانی بہبود کے موافق حالات پیدا کرنے کے اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔
یورپ میں کیلون سے لے کر مشرقِ وسطیٰ میں ہوبز تک
کہاوت مشہور ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی نہیں ہے بلکہ اس کی بازگشت گونجتی رہتی ہے۔ مشرقِ وسطیٰ میں سیاسی اسلام کا ابھرنا اپنی وضع میں انوکھا واقعہ ضرور ہے مگر اس نے جو راستہ اختیار کیا اور جس طرح کے بحران کو جنم دیا وہ مغرب کے اپنے ماضی ہی کی بازگشت ہے۔ مسلم دنیا میں سیاسی اسلام اور لادینیت کی لڑائی اب پیچیدہ ہوچکی ہے مگر سوال یہ ہے کہ معاشرے میں کون بالادست ہے اور اس سوال کا دار و مدار قانون کے مآخذ اور اس کے متن پر ہے۔ اسلام پسندوں کا اصرار شریعت پر ہے، یعنی قانون کی تشکیل قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی۔ لادین طبقہ کہتا ہے کہ قانون کی بنیاد انسانی عقل اور تجربے پر ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ کے نزدیک تھوڑا بہت عمل دخل قابلِ قبول ہے۔
مشرقِ وسطیٰ میں لادینیت نے یورپی نوآبادیاتی نظام کے ساتھ قدم جمائے۔ آزادی کے بعد مسلمان اشرافیہ کی اکثریت نے اسے اس لیے اپنا لیا کیونکہ طاقتور یورپی ریاستوں نے خلافت کہلانے والی سلطنتِ عثمانیہ کو ہزیمت کے ساتھ شکست دی تھی۔ لیکن پھر لادینیت کو اسلام اِزم کا ایک دھچکا لگا۔ یہ درست ہے کہ اسلام پسند اپنے نظریے کہ ساتھ ’’ازم‘‘ نہیں لگاتے اور اسے وہی اسلام بتاتے ہیں جو اپنی ابتدا میں تھا لیکن ان کے نظامِ عقائد کے بہت سے مآخذ جدید ہیں۔ بیسویں صدی کے ربعِ ثانی کے دوران اسلام پسندوں نے اس خیال سے مزاحمتی تحریکیں منظم کیں کہ لادین دورِ حکومت میں متقی مسلمان بن کر رہنا مشکل ہے۔ ۱۹۵۰ء کی دہائی میں اس خیال نے مزید تقویت حاصل کی اور اسلام پسندوں نے ریاست کی جانب سے شریعت کے نفاذ کی وکالت شروع کردی۔ ۱۹۶۰ء کی دہائی تک لادینیت کو سبقت حاصل تھی مگر ۱۹۶۷ء میں لادین مصر کی اسرائیل کے ہاتھوں شکست، ۱۹۷۹ء کے ایرانی انقلاب اور ۹۱۔۱۹۹۰ء کی خلیجی جنگ نے پانسہ سیاسی اسلام کے حق میں پلٹ دیا۔
ایک اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی اسلام کی جیت ہوچکی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج کا مسلمان نہ تو پورا لادین ہے اور نہ ہی پکا اسلام پسند، لیکن مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقا کا عام مسلمان اب شدت پسندی کی طرف مائل ہوتا جارہا ہے۔ پیو تحقیقی مرکز (Pew Research Center) کی ۲۰۱۳ء میں کرائی گئی رائے شماری بتاتی ہے کہ مصر، عراق، اردن، مراکش اور فلسطینی علاقوں کی غالب اکثریت شریعت کو ملکی قانون کے طور پر نافذ دیکھنا چاہتی ہے۔ ۲۰۱۲ء کے ایک گیلپ سروے نے ظاہر کیا کہ مصر، لیبیا، شام، تیونس اور یمن میں خواتین بھی مردوں ہی کی طرح شریعت کی حامی ہیں۔ اسلام پسندوں میں بھی مذہب کے عوامی زندگی میں عمل دخل اور حکومت میں علما کے کردار سے متعلق مختلف آرا پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آزاد خیال حکمرانوں نے بھی اسلام ازم کے کچھ خیالات کو تسلیم کرلیا ہے۔
اس پیش قدمی کے باوجود، سیاسی اسلام ابھی تک اپنی بقا کے بارے میں غیریقینی صورت حال سے دوچار ہے۔ شروع شروع میں بیرونی مبصرین نے اسے جدیدیت سے مطابقت نہ رکھنے والا خیال کہہ کر رد کیا، آج کے ماہرین ایک دوسرے کو یقین دلا رہے ہیں کہ داعش جیسے جہادی گروہوں کی جانب سے خودکش حملوں اور سر قلم کیے جانے سمیت مشرقِ وسطیٰ میں ابھرتی تشدد کی یہ لہر سیاسی اسلام کے چل چلاؤ کی نشانی ہے۔
پھر بھی نظریاتی کشمکش کے حوالے سے یورپ کی اپنی تاریخ مشرقِ وسطیٰ کو یہ کلیدی سبق دیتی ہے کہ اسلام اِزم کو اتنا بے وقعت بھی نہ سمجھا جائے۔ یورپ میں مذہبی جنگوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ بظاہر ایک فرسودہ نظریے کو غیر اہم سمجھنا کیوں بہت خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ جب کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کی دشمنی لوگوں کے جان اور مال کو برباد کررہی تھی، اس وقت کی جنگوں میں کئی مواقع ایسے آئے، جب منطق اور ترقی نے بظاہر دشمنیوں کو ختم کرنے میں مدد دی۔ ایسا کئی دفعہ ہوا، مثلاً ۱۵۵۵ء میں جرمن علاقوں کے مذہبی حق رائے دہی پر رضامندی کے وقت اور ۱۵۹۰ء کی دہائی میں جب فرانسیسی مذہبی جنگوں کے بعد پروٹسٹنٹ ولندیزی جمہوریہ (Protestant Dutch Republic) نے کیتھولک ہسپانیہ سے آزادی حاصل کی تو لگا کہ بحران ٹل گیا ہے۔ شہزادے، اشرافیہ، شہری کونسلیں اور ان کی رعایا بظاہر پائیدار امن پر یکسو ہوگئے تھے۔ عملیت پسند سیاسی فراست نے عنان سنبھال کر ایک نئے یورپ کی امید باندھ دی تھی جہاں ریاستوں کو نظریاتی مفادات کے بجائے مادی مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔
لیکن یورپ سے نظریاتی تشدد کا خاتمہ نہ ہوسکا کیونکہ اسے ہوا دینے والا بالادستی کا بحران جوں کا توں کھڑا تھا۔ بہت سے یورپی باشندے یہی سوچتے تھے کہ مستقل سیاسی استحکام کے لیے مذہبی ہم آہنگی ضروری ہے۔ جب تک وہ ایسا سمجھ رہے تھے، اس وقت تک کوئی بھی ذرا سی چنگاری انہیں دوبارہ شدت پسند مخالفانہ گروہوں میں منتشر کرسکتی تھی۔ اور ۱۶۱۸ء میں بالکل ایسا ہی ہوا جب بوہیمیا میں پروٹسٹنٹ بغاوت نے یورپ کو تیس سالہ جنگ میں جھونک دیا۔ اُس صدی کے آخر میں جب تک یورپیوں نے مذہب کو سیاست سے الگ نہیں کردیا، اس وقت تک مذہبی عقائد اپنی شعلہ فشاں طاقت کا مظاہرہ کرتے رہے۔
نظریات کو بے وقعت سمجھنے کی ذرا مختلف مثال نسبتاً حالیہ زمانے میں سامنے آئی جب بیسویں صدی میں عالمی سطح پر لبرل ازم اور کمیونزم کا ٹاکرا ہوا۔ ۱۹۳۰ء کی دہائی کے معاشی بحران (Great Depression) نے بہت سے مغربی دانشوروں کو یہ باور کرا دیا کہ آزاد خیال جمہوریت ایک ایسا تصور تھا جس کا زمانہ اب گزر چکا ہے۔ مرکزیت پسند جابر ریاستیں عارضی طور پر نئے معاشی و سماجی بحران سے اچھی طرح نمٹنے لگیں جسے دیکھ کر بہت سے مفکرین کمیونزم کے شیدا ہوگئے۔ کچھ نے جوزف اسٹالن کے زیرِ اقتدار سوویت یونین کا دورہ کرکے اسے کھلے عام سراہا جہاں صنعت کاری تیزی سے ہورہی تھی اور مزدور کبھی ہڑتال نہیں کرتے تھے۔ ان جذبات کو امریکی صحافی لنکن اسٹیفنز نے یوں قلم بند کیا: ’’میں مستقبل میں ہوکر آچکا ہوں اور یہ تجربہ کامیاب رہا!‘‘ لیکن ظاہر ہے کہ آخر میں آزاد خیال جمہوریت نے انگڑائی لی اور کامیاب ہوگئی۔
بات یہ نہیں ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں اسلام ازم کی کامیابی یقینی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خود کو بہت کچھ سمجھنے والے لوگ کبھی کبھی متبادل سیاسی نظام کو نظر انداز کرتے ہیں جس کے نتائج سنگین بھی ہوسکتے ہیں۔ سیاسی اسلام کے سخت جان ہونے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ باہر سے دیکھنے والوں نے اس نظام کو ہمیشہ کمتر سمجھا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر کسی نظریے کو ریاستی سرپرستی حاصل ہوجائے تو وہ زیادہ عرصے زندہ رہ سکتا ہے جیسا کہ ۱۹۳۰ء کی دہائی میں لبرل جمہوریت کے ساتھ ہوا اور آج اسلام ازم کے ساتھ ہورہا ہے۔ سیاسی اسلام کامیابی کی دوڑ سے باہر ہونے نہیں جارہا، بلکہ ہوسکتا ہے کہ یہ اپنی دوسری فتح حاصل کرلے۔
خدا کے نام پر؟
بہت سے پرانے مسابقتی نظریات کی طرح سیاسی اسلام میں بھی یک رنگی نہیں ہے۔ اسلام پسند ایک شریعت کا اتباع تو کرتے ہیں لیکن ان میں بہت سی شاخیں ہیں، مثلاً سُنّی اور شیعہ، شدت پسند اور اعتدال پسند، قوم پرست، بین الاقوامیت کے داعی اور سامراجیت کے حامی تک موجود ہیں۔ اس تنوع نے مغرب میں اس بحث کو جنم دیا ہے کہ آیا امریکا اور اس کے اتحادیوں کو شدت پسند تحریکوں کی حوصلہ شکنی کے لیے جدید اعتدال پسند اسلام ازم کو قبول کرلینا چاہیے یا نہیں۔ جو لوگ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں، اُن کے نزدیک اسلام ازم پورے کا پورا مغرب دشمنی پر مبنی ہے۔ جن لوگوں کا جواب اثبات میں ہے وہ کہتے ہیں اسلام ازم خود اندرونی طور پر منقسم ہے۔
اس بحث میں کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ کسی بھی نظریے کے مخالفین اس میں موجود دراڑوں کے ذریعے اپنے حق میں پنپنے والا تنازع اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری مغربی تاریخ میں بیرونی طاقتوں نے بارہا ’’تقسیم کرو اور جیت لو‘‘ کے حربے آزمائے جن کے ملے جلے نتائج برآمد ہوئے اور کبھی کبھار ایسی کوششیں انہی کے گلے بھی پڑگئیں۔ مذہبی جنگوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طویل تنازع نے یورپ پر حاوی نظریات میں پھوٹ ڈال دی اور نتیجتاً پنپنے والے کچھ ضمنی افکار اصل نظریات پر ہی غالب آگئے۔ پروٹسٹنٹ ازم کی ابتدا لوتھرینزم کے طور پر ہوئی جو فوراً ہی سوئٹزرلینڈ میں زوئنگلین ازم (Zwinglianism) اور جرمنی میں انا باپتزم (Anabaptism) کی شکل میں نمودار ہوا اور پھر فرانس میں اس نے کیلون ازم اور انگلستان میں اینگلیکن (Anglican) روپ دھار لیا۔ کیلون ازم اور لوتھرینزم کے پیروکار آپس میں بار بار لڑے اور کسی بھی کیتھولک گروہ سے زیادہ ایک دوسرے کے دشمن ثابت ہوئے۔ مقدس رومی سلطنت پر حکمراں ہیبس برگ (Habsburg) خاندان نے ان اختلافات کو ہوا دینے کے لیے انتھک کوششیں کیں۔ لیکن آخر میں بہرحال یہ حکمت عملی ناکام ہوئی کیونکہ کیلون ازم کمزور نہیں پڑا بلکہ اس نے تیس سالہ جنگ کے دوران لوتھرینزم کے ساتھ مشترکہ محاذ بنا لیا۔
بیرونی طاقتوں کے لیے یہی ترکیب باقی بچتی ہے کہ وہ کسی نظریے کے مقابلے میں دیگر نظریاتی عناصر کو اپنی جانب مائل کریں اور انہیں مدد و حمایت فراہم کریں۔ ایسا کرنا آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سوویت اثر و رسوخ محدود کرنے کی خاطر امریکی صدر ہنری ٹرومین نے یہ معلوم کرنے میں بڑی چابکدستی دکھائی کہ مغربی یورپ میں بائیں بازو کی کون سے جماعتیں امریکی اتحادی بن سکتی ہیں۔ وہ اس درست نتیجے پر پہنچے کہ اٹلی کے کمیونسٹ اور سوشلسٹ سوویت یونین کی حمایت اور امریکی مارشل پلان کی مخالفت میں متحد ہیں۔ ٹرومین نے پھر عیسائی جمہوریت پسندوں (Christian Democrats) کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں ۱۹۴۸ء کا اہم انتخاب جیتنے میں مدد دی۔ البتہ فرانس میں ٹرومین کو یہ اندازہ ہوا کہ سوشلسٹ کمیونزم کے مخالف ہیں لہٰذا ان کے ساتھ معاہدہ کرکے فرانس کو امریکا کا مشکل مگر پائیدار اتحادی بنالیا۔
بیرونی طاقتوں کی یہ کھلی اور چھپی مداخلت بالادستی کے طویل ہوتے بحران کی ایک اور واضح نشانی ہے۔ اسلام ازم اور لادینیت کے حالیہ ٹکراؤ میں بھی بہت سے بیرونی کرداروں نے یا تو خود کو دیگر ریاستوں کے اندرونی معاملات میں الجھا لیا ہے یا پس پردہ رہ کر فوجی مداخلت کرڈالی ہے۔ ان بیرونی مداخلتوں پر کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی ہے۔ خاص طور پر افغانستان، عراق اور لیبیا میں امریکی مداخلت کو ایسی غیرمنطقی مہم جوئی قرار دیا گیا جو مؤثر ریاستی سرگرمیوں کے دائرے میں نہیں آتی۔ لیکن درحقیقت کسی بھی عظیم طاقت کی جانب سے دوسرے ملک کی حکومت کو بچانے یا گرانے کے لیے قوت کا استعمال کوئی نئی بات نہیں۔ بیرونی مداخلتیں کسی بھی نظریاتی کشمکش کا لازمی جز ہوتی ہیں، انہیں علیٰحدہ، بے وقوفانہ یا غیر متعلق نہیں کہا جاسکتا۔ پچھلے ۵۰۰ برس کے دوران ایسی ۲۰۰ سے زائد مداخلتیں ہوچکی ہیں جو زیادہ تر بالادستی کے علاقائی بحران کے دوران کی گئیں اور یہی اس وقت مشرقِ وسطیٰ میں ہورہا ہے۔
اس طرح کی کشمکش کے دوران پیدا ہونے والی گہری خلیج بار بار ہونے والی اس مداخلت کی وجوہات جاننے میں مدد دیتی ہے۔ نظریاتی تنازعات کے باعث اکثر اتنا سخت معاشرتی تناؤ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اپنوں کے بجائے ان غیروں کے طرف دار ہوجاتے ہیں جن سے ان کے خیالات ملتے ہیں۔ یہی ٹکراؤ بیرونی کرداروں کے ساتھ قوموں اور ملکوں کی دوستی یا دشمنی کا تعین کرتا ہے۔ مرکزیت ان بڑی طاقتوں کو حاصل ہوتی ہے جو کسی بھی فریق کو بالادست بنانے کی حیثیت رکھتی ہوں۔ ادھر بیرونی کرداروں کے لیے اس طرح کے بحرانات نئے دوست بنانے یا نئے دشمنوں کو ابھرنے سے روکنے کا ایک موقع ثابت ہوتے ہیں۔
ضروری نہیں کہ مداخلت کاروں کا تنازع سے کوئی مذہبی مفاد وابستہ ہو، کبھی کبھی مادی مفادات بھی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ مواقع پر نظریاتی اور مادی مفادات مل کر مداخلت کا جواز پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً ۲۰۱۱ء میں عرب بہار کے دوران سنی اکثریتی سعودی عرب نے بحرین میں شیعی انقلاب روکنے کے لیے فوج بھیج کر نہ صرف شیعہ اسلام کا راستہ روکا بلکہ شیعہ اکثریتی ایران کے لیے بھی دروازے بند کردیے۔ کچھ ہی عرصے بعد ایران نے شام میں مداخلت کرکے بشار الاسد کی اس لیے مدد کی تاکہ سنی باغی کامیاب ہوکر سعودی عرب کے طرف دار نہ ہوجائیں۔ اس طرح کی کارروائیوں نے ان خدشات کو تقویت دی ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں اب ناعاقبت اندیش نظریاتی ریاستیں وجود میں آکر علاقائی استحکام کو تباہ کریں گی۔ مثلاً کچھ مبصرین کو خدشہ ہے کہ ایران نے اگر جوہری ہتھیار بنالیے تو وہ انہیں مشرقِ وسطیٰ میں طاقت کا توازن ناپید کرنے کے لیے استعمال کرکے ایک بڑی تباہی کو دعوت دے سکتا ہے۔
تاریخ ایسے خدشات پر کوئی فیصلہ تو صادر نہیں کرتی البتہ یہ ضرور بتاتی ہے کہ ایک ریاست بیک وقت نظریاتی اور منطقی ہوسکتی ہے۔ نظریہ پرستوں کی حکومت کے سامنے علاقائی توازن کو یکسر تبدیل کرنے جیسے نظریاتی مقاصد ہوسکتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے وہ منطقی اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ ایسے اقدامات میں اس مرحلے پر پسپائی اختیار کرلینا بھی شامل ہے جب جارحیت بہت مہنگی پڑنے لگے اور ہر اس موقع پر مداخلت بھی ہوسکتی ہے جب جغرافیائی سیاست اس کی اجازت دے۔
مذہبی جنگوں کے دوران پلاٹی نیٹ (Palatinate) نامی جرمن خطے کا طرزِ عمل ان دونوں ممکنات پر محیط رہا۔ وہاں کے حکمران عسکریت پسند کیلوینسٹ (Calvinists) تھے جنہوں نے مقدس رومی سلطنت سمیت پورے یورپ سے کیتھولک اجارہ داری ختم کرنے کی بھرپور جدوجہد کی۔ انہوں نے کیتھولک طاقتوں کا زور توڑنے کے لیے بارہا پروٹسٹنٹ اتحاد تشکیل دیے اور کیلوینسٹوں کی مدد کے لیے کئی مواقع پر فرانس اور نیدرلینڈ فوج بھیجی۔ سولہویں صدی میں بڑے عرصے تک ان کے مقاصد نظریاتی ہونے کے ساتھ ساتھ منطقی بھی رہے کیونکہ جب کبھی انہیں طاقتور ہیبس برگ کی جانب سے سخت مزاحمت ملی یا پروٹسٹنٹ ساتھیوں نے سرد مہری دکھائی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ مگر پھر کیتھولک حکومت کے حامل بوہیمیا خطے کے کیلوینسٹ باغیوں نے جب پلاٹی نیٹ حکمران فریڈرک پنجم کو دعوت دی کہ وہ ہیبس برگ حاکم کو شکست دے کر ان کا بادشاہ بن جائے تو اس نے یہ دعوت قبول کرلی۔ ۱۶۱۹ء میں اس نے بوہیمیا پر اپنے اقتدار کا دعویٰ کیا حالانکہ ہیبس برگ حکمرانوں کے ردعمل کا خدشہ بھی تھا اور زیادہ تر یورپی پروٹسٹنٹ بھی کھلے بندوں اس کی حمایت سے کترا رہے تھے۔ بالآخر خدشہ درست ثابت ہوا جب ہیبس برگ خاندان نے فریڈرک کی فوج کو کچل ڈالا اور پلاٹی نیٹ تک رسائی حاصل کرکے وہاں پروٹسٹنٹ ازم کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ یہ تیس سالہ جنگ کے ابتدائی اقدامات تھے۔
جس دیے میں جان ہوگی، وہ دیا رہ جائے گا!
طول پکڑنے والے تمام علاقائی نظریاتی تنازعات کی طرح اسلام ازم اور لادینیت کی جنگ بھی ایک روز ختم ہوجائے گی۔ لیکن یہ کس انداز میں ہوگا اور مشرقِ وسطیٰ میں جمہوریت کے کیا امکانات ہیں، یہ البتہ ایک کھلا سوال ہے۔
مغربی تاریخ بتاتی ہے کہ بالادستی کے بحران عموماً تین طریقوں سے ٹلتے ہیں: یا تو کوئی فریق فیصلہ کن فتح حاصل کرلے، یا برسرِ پیکار فریقین کے نزدیک تنازع غیر متعلق ہوجائے، یا پھر کوئی ایسی حکومت قائم ہو جو متصادم نظریات کو بظاہر ناممکن نظر آنے والے انداز میں مربوط کردے۔ حالیہ تنازع میں پہلا منظرنامہ تو ابھرتا دکھائی نہیں دیتا۔ اسلام ازم میں یک رنگی نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ فتح کی صورت میں شیعہ سنی، اعتدال پسند اور شدت پسند، جمہوری یا بادشاہی، کون سا طبقہ سبقت حاصل کرے گا۔ تاہم دیگر دو منظرناموں کو قابل غور قرار دیا جاسکتا ہے۔
ایسے مشرقِ وسطیٰ کا تصور بظاہر محال ہے جو بالادستی کے موجودہ بحران پر قابو پالے، تاہم ماضی میں مغرب کا ایک بحران اسی انداز میں حل ہوا۔ ابتدائی جدید یورپ مذہبی کشمکش پر قابو پانے میں اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ وہاں نئی حکومتوں کے قیام نے نظریاتی اختلافات کو غیر مؤثر کردیا تھا۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقے اپنے اپنے عقائد پر جمے رہے لیکن انہوں نے مکمل بالادستی کا خیال چھوڑ کر ریاست اور کلیسا کے مابین جدائی کو تسلیم کرلیا۔ مشرقِ وسطیٰ میں بھی ایسا ہوسکتا ہے اگر مسلمانوں کے عوام اور خواص قانون اور عوامی زندگی پر اسلامی عقائد لاگو کرنے کے معاملے کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائے رکھیں۔ تاہم اگر مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو مدنظر رکھا جائے تو ایسا ہونا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔
دوسرا راستہ یہ ہے کہ متصادم نظریات ایک دوسرے کے اداروں اور طور طریقوں کو کسی حد تک اپنا کر ایک ہی دھارے میں شامل ہوجائیں۔ یورپ میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا جب ۱۷۷۰ء کی دہائی سے لے کر ۱۸۵۰ء کی دہائی تک یہ براعظم بادشاہتوں میں منقسم تھا۔ بادشاہ چاہتے تھے کہ اقتدار وراثت کی طرح حصے میں آئے جبکہ جمہوریت پسند منتخب حکومتوں کے خواہاں تھے۔ دونوں تصورات ابتدا میں متحارب دکھائی دیے اور بادشاہتیں جمہوری بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف رہیں۔ لیکن جبر کے اس دور کے بعد یورپی بادشاہوں نے متوسط طبقے کے ساتھ ایک سودا کرلیا۔ برطانیہ کی دیکھا دیکھی آسٹریا، فرانس، اٹلی اور پرشیا (Prussia) میں نئی طرز کی حکومتیں قائم ہوگئیں اور پارلیمانی قدغنوں اور وسیع عوامی حقوق کی حامل بادشاہت کے اس نظام کو ’’آزاد قدامت پسندی‘‘ (liberal conservatism) کا نام دیا گیا۔
اس کہانی کا حتمی تاریخی سبق یہ ہے کہ کسی بھی نظریے یا متعدد نظریات کی کامیابی کا دار و مدار اکثر ریاستی طاقت کے حصول پر ہوتا ہے۔ یورپ میں آزاد قدامت پسندی برطانیہ کی مرہون منت ہے جس نے عملی طور پر اسے نافذ کردکھایا۔ وہاں طویل عرصے تک ایسی آئینی بادشاہت رہی جس نے روایت اور تجدید کو یکجا کردیا۔ برطانیہ بلاشبہ دنیا کی کامیاب ترین ریاست رہی جس کے پاس سب سے بڑی معیشت، وسیع و عریض سلطنت اور ایک مثالی طور پر مستحکم سماجی نظام رہا۔ اس کے مخلوط طرزِ حکومت کو پورے براعظم میں اپنالیے جانے کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں تھی کہ عملاً یہ نظام قابلِ نفاذ ثابت ہوگیا تھا۔
مسلم دنیا میں بھی اس سے ذرا مختلف مخلوط حکومت نے اپنا استحکام ظاہر کیا ہے جسے بسا اوقات ’’اسلامی جمہوریت‘‘ قرار دیا جاتا ہے۔ ماہرین ایک عرصے سے یہی سمجھتے رہے ہیں کہ جمہوریت اور اسلام ازم موروثی اعتبار سے متضاد ہیں مگر کچھ اسلام پسندوں اور جمہوریت کے حامیوں نے مختلف ممالک میں ان دو نظاموں کو فکری اور عملی سطح پر یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ۲۰۱۱ء سے ۲۰۱۳ء تک مصر میں اخوان المسلمون کے سیاسی بازو حزب حریت و عدالت (Freedom and Justice Party) نے کٹھن حالات میں خود کو ایک ایسی معتدل قوت کے طور پر ظاہر کیا جو مذہبی اور نظریاتی تنوع کو برداشت کرسکتی تھی۔ یہ کوشش بالآخر ناکام ہوئی کیونکہ صدر مرسی نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کیے اور فوج نے انہیں معزول کردیا۔ جب سے اب تک مصر میں سرے سے جمہوریت ہی ناپید ہے لیکن اگر دوبارہ تجربے کا موقع ملے تو یہ ملک اپنے حجم اور استعداد کے اعتبار مثالی ریاست بن سکتا ہے۔
اسلام ازم اور جمہوریت کو ایک لڑی میں پرونے کی زیادہ کامیاب مثال تیونس میں النہضہ نامی سیاسی جماعت نے قائم کی جس نے کھلے عام اسلام ازم کی بات کرنے کے باوجود ۲۰۱۴ء میں جمہوری انتخابات کرادیے۔ تیونس اتنی بڑی ریاست نہیں کہ مثال بن سکے لیکن یہ عرب بہار کے نتیجے میں ابھرنے والا سب سے روشن ستارا ہے جو کم سے کم ممکنات سے آگاہ ضرور کردیتا ہے۔
زیادہ تر انحصار اس بات پر ہے کہ خطے کے دو طاقتور ترین مسلم ممالک یعنی ایران اور ترکی کی سیاسی ترجیحات کیا ہیں۔ دونوں ہی ممالک عرب نہیں ہیں لیکن علاقائی اثر و رسوخ کی ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ سرکاری طور پر جمہوریہ کہلانے والا ایران ۱۹۷۹ء کے انقلاب کے بعد سے خود کو اسلام ازم کا عملی معیار قرار دیتا ہے جہاں کسی حد تک مسابقتی انتخابات تو ہوتے ہیں مگر حتمی اختیارات رہبر معظم خامنہ ای ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ مگر عرب بہار کے بعد ایران نے شام میں صدر بشار الاسد کی جس طرح حمایت کی، اُس سے سنی عربوں کی غالب اکثریت اس سے متنفر ہوگئی ہے اور اس کے مثالی ریاست بننے کے امکانات دھندلا گئے ہیں۔ اور پھر ۲۰۰۹ء کے مشکوک انتخابات کے بعد ایسا مشکل ہی دکھائی دیتا ہے کہ اس کے ہمسائے اب اس کی تقلید کریں۔ گویا جب تک ایران اسلام ازم کی مثال بنا رہے گا، اسلام ازم مشکل میں رہے گا۔
ترکی کی کہانی البتہ مختلف ہے۔ سرکاری اعتبار سے لادین کہلانے والا یہ ملک مسلسل اسلام پسندی کی جانب مائل ہے۔ گزشتہ تین برسوں میں ترکی نے خود ایک نئی اور مربوط اسلامی جمہوریت کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ حکمراں ترقی و انصاف پارٹی کو انتخابات میں مسلسل فتح ہورہی ہے جس کی باگ ڈور صدر رجب طیب ایردوان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جماعت اس طرزِ حکومت کو ’’اسلامی‘‘ کے بجائے ’’قدامت پسند‘‘ قرار دیتی ہے لیکن یہ نظام بہرحال اسلامی جمہوریت کی ہی ایک شکل ہے۔ عرب بہار کی ابتدا میں ہی ترکی خطے کے عوام کے دلوں میں گھر کر چکا تھا اور اب اپنا دائرئہ اثر مسلسل بڑھا رہا ہے۔ لیکن جب بات ہو مخلوط اسلامی جمہوری حکومت کی تو پھر اس نظام میں اتنی رعنائی نہیں رہتی جس کی بڑی وجہ ایردوان کا آمرانہ طرزِ عمل ہے۔ ترکی ایک مثالی مخلوط حکومت کا نمونہ پیش کرسکتا ہے مگر فی الحال وہاں پرانے انداز کی شخصی آمریت جمہوری عنصر پر غالب آرہی ہے۔
لڑائی کی وجوہات
ماضی کے بہت سے نظریاتی تنازعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ مبصرین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مشرقِ وسطیٰ میں بحران کی اصل وجہ نظریاتی ہے بھی یا نہیں۔ بہت سے ناقدین دور کی کوڑی لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے یورپی اور اب امریکی سامراجیت نے مسلمانوں کی تضحیک کرنے کے ساتھ ساتھ انفرادی اور معاشرتی سطح پر اپنا مستقبل خود تعمیر کرنے کی ان کی صلاحیت بہت محدود کردی ہے۔ اس سلسلے میں امریکا کی خطے میں عسکری موجودگی اور اسرائیل کی حمایت کو بڑھتی ہوئی خونریزی کی وجہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے دلائل اس حقیقت کو نظر انداز کردیتے ہیں کہ دنیا تو طاقت سے محروم مضطرب افراد اور گروہوں سے بھری ہوئی ہے اور امریکی اجارہ داری تقریباً ساری دنیا میں ہی ہے۔ لیکن پھر بھی مشرقِ وسطیٰ میں جیسی مسلسل بدامنی، جبر، دہشت گردی، سفاکیت اور بیرونی مداخلت ہے، ویسی دنیا میں شاید ہی کہیں اور ملے۔
کچھ لوگ غربت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس دولت اور مواقع ذرا زیادہ ہوتے تو بحران ٹل جاتا۔ مگر دنیا کے بہت سے غریب معاشرے اس دلیل کو بھی کالعدم کردیتے ہیں کیونکہ ان میں سے بیشتر مشرقِ وسطیٰ کی اوسط درجے کی ریاستوں سے زیادہ بدحال ہیں مگر ایسی افراتفری سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر غریبی ہی سب سے بڑی وجہ ہوتی تو افریقی صحرائے اعظم سے متصل ممالک دہشت گردی، انقلابی لہروں اور بیرونی مداخلت کا اس سے کہیں زیادہ شکار ہوتے۔ شواہد ہمیں کسی اور نتیجے تک پہنچا رہے ہیں: یعنی بے طاقتی اور غربت بلاشبہ کلیدی عناصر ہیں مگر مشرقِ وسطیٰ آج کل جس صورت حال سے دوچار ہے، وہ اُسی وقت پیدا ہوسکتی تھی جب یہ دونوں عناصر علاقائی سطح پر بالادستی کے ایک طویل بحران سے منسلک ہوجائیں۔
اچھی خبر یہ ہے کہ شاید امریکا دیر پا انداز میں معتدل حکومت چلانے والے ملکوں اور جماعتوں کی حمایت کرے گا، چاہے ان کا نظام مکمل طور پر لادین نہ بھی ہو۔ مگر بری خبر یہ ہے کہ یہ سب ہونے کی صرف توقع ہی کی جاسکتی ہے کیونکہ طاقتور امریکا بھی خطے کے تمام مسائل حل نہیں کرسکتا۔ چونکہ ہر فریق امریکی مداخلت کو متعصبانہ قرار دے گا، اس لیے امریکا کے لیے اپنے مفادات کا تحفظ ہی بہتر ہے۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو کبھی کبھی کچھ جگہوں پر طاقت کے استعمال کی متقاضی ہوگی۔ مگر جیسا کہ مذہبی جنگوں کے دوران سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم مسلم طاقت بھی سولہویں صدی میں عیسائیوں کے اختلافات ختم نہیں کراسکی تھی، ویسے ہی آج کے مشرقِ وسطیٰ میں بھی کوئی بیرونی کردار امن نہیں لاسکتا۔ صرف مسلمان خود ہی اپنے نظریاتی اختلافات کو دور کرسکتے ہیں۔
(مترجم: حارث رقیب عظیمی)
John M. Owen IV
“From Calvin to the Caliphate”.
(“Foreign Affairs”. May/June 2015)
 بھلا ہو نئے محب وطن اور متحدہ سے منحرف شدہ پاک سر زمین پارٹی کے بانی رہنما مصطفی کمال کا کہ انہوں نے 14سال بعد، معصوم و فرشتہ صفت پاکستانی حکمرانوں اور مقتدر اداروں کو، بذریعہ پریس کانفرنس اور انٹرویو لفظی طور پر آگاہ اور قائل کیا کہ 14 سال سندھ کا گورنر رہنے والا شخص دراصل رشوت العباد ہے اور قومی مجرم ہے۔ مصطفی کمال کے ا نکشافات کے بعد، مقتدر حلقوں کی طرف سے گورنر سندھ کے لیے بے اعتنائی کا اظہار تو محسوس کیا جا رہا تھا جو بالآخر گورنر سندھ کی تبدیلی پر منتج ہوا۔
بھلا ہو نئے محب وطن اور متحدہ سے منحرف شدہ پاک سر زمین پارٹی کے بانی رہنما مصطفی کمال کا کہ انہوں نے 14سال بعد، معصوم و فرشتہ صفت پاکستانی حکمرانوں اور مقتدر اداروں کو، بذریعہ پریس کانفرنس اور انٹرویو لفظی طور پر آگاہ اور قائل کیا کہ 14 سال سندھ کا گورنر رہنے والا شخص دراصل رشوت العباد ہے اور قومی مجرم ہے۔ مصطفی کمال کے ا نکشافات کے بعد، مقتدر حلقوں کی طرف سے گورنر سندھ کے لیے بے اعتنائی کا اظہار تو محسوس کیا جا رہا تھا جو بالآخر گورنر سندھ کی تبدیلی پر منتج ہوا۔
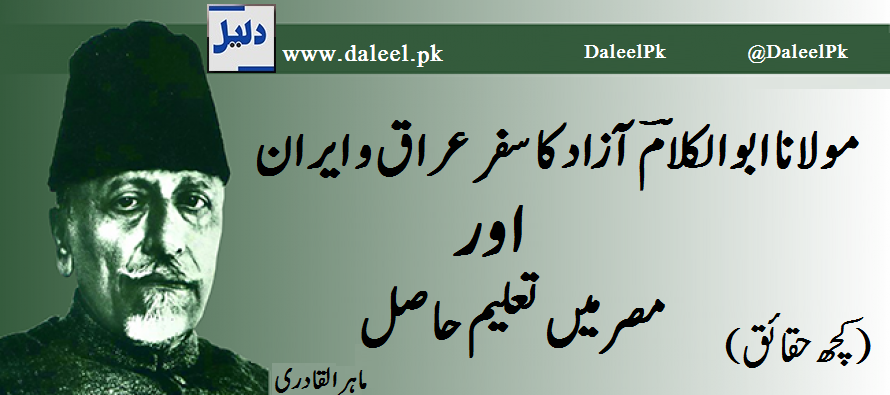

 “صاب اب میرا کام ہو جائے گا نا”
“صاب اب میرا کام ہو جائے گا نا”
