 اکثر یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے کہ قوم کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ قوم کسی خطے میں رہنے والے افراد سے مل کر بنتی ہے یا ایک زبان بولنے والے مل کر ایک قوم بناتے ہیں؟ ایک رنگ کے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں یا مشترک مفاد کے حامل لوگ ایک قوم کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں؟ بھانت بھانت کا فلسفہ سننے کو ملتا ہے۔ لبرل اور سیکولر خواتین و حضرات مصر ہیں کہ ایک خطے میں رہنے والے اور مشترک تاریخ و تمدن رکھنے والے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں۔ پھر قوم، ملت اور امت کے الفاظ کی بھی تشریح کی جاتی ہے اور ان میں فرق بیان کیے جاتے ہیں۔
اکثر یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے کہ قوم کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ قوم کسی خطے میں رہنے والے افراد سے مل کر بنتی ہے یا ایک زبان بولنے والے مل کر ایک قوم بناتے ہیں؟ ایک رنگ کے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں یا مشترک مفاد کے حامل لوگ ایک قوم کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں؟ بھانت بھانت کا فلسفہ سننے کو ملتا ہے۔ لبرل اور سیکولر خواتین و حضرات مصر ہیں کہ ایک خطے میں رہنے والے اور مشترک تاریخ و تمدن رکھنے والے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں۔ پھر قوم، ملت اور امت کے الفاظ کی بھی تشریح کی جاتی ہے اور ان میں فرق بیان کیے جاتے ہیں۔
سیکولر طعنہ دیتے ہیں کہ ایشیا میں پیدا ہو کر عربوں کی تاریخ کو کس منہ سے اپنا قرار دیتے ہو؟ جو عروج و زوال عربوں کی تاریخ میں وقوع پذیر ہوئے اس کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ عربوں کو جاتا ہے، تم کیوں لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہوتے ہو؟ عرب تو تمہیں لفٹ تک نہیں کراتے تم کس امت اور کس قوم کے بات کرتے ہو؟ جس تاریخ کو تم مسلمانوں کی تاریخ گردانتے ہو وہ دراصل عربوں کی تاریخ ہے ایشیا اور خصوصا جنوبی ایشیا میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کا اس سے کیا لینا دینا؟
اسلام کا نظریہ قومیت بڑا واضح ہے. وہ مذہب یا عقیدے کو اس کی بنیاد بتاتا ہے جسے ایمان بھی کہا جاتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہاں میں بھی قوم کی بنیاد انبیا و رسل ہی بتائے گئے ہیں یعنی ایک نبی کے ماننے والے اور ایک عقیدہ رکھنے والے لوگ ایک قوم ہیں۔ جو کسی نبی کا انکار کر دے وہ اس قوم سے نکل گیا۔ قیامت کے دن بھی تمام انسان اپنے اپنے انبیاء کی قیادت میں اکٹھے ہوں گے۔ کوئی نبی صرف ایک امتی کے ساتھ آئے گا کسی کے ساتھ ذیادہ امتی ہوں گے۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد سب سے ذیادہ ہو گی جس پر آپ ﷺ فخر کریں گے۔
ہمارے چند دانشور ایک خطے سے متعلق نسلوں کو ایک قوم گردانتے ہیں جس کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ مذہب سے الرجک ہونے کے باعث جس تہذیب اور تاریخ کو اسلام پسند مسلمانوں کی تاریخ کہہ کر بیان کرتے ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو عربوں کی یا ترکوں کی تاریخ ہے تم اپنے آپ کو اس سے نتھی نہ کرو۔ مگر ہمارے ذہن میں اس سے یہ سوال کلبلا رہا ہے کہ پھر تاریخ کہاں جا کر رکے گی بابا گرو نانک پر یا چانکیہ پر؟ راجہ داہر کو اپنا جد امجد قرار دیں گے یا چندرگپت موریا کو؟ پھر یہاں ہی کیوں رکیں؟ اس طرح تو سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب کی تاریخ مشترک ہونی چاہیے۔
اسلامی تاریخ پر غور کریں تو قوم کی تشکیل سے متعلق بڑے غیر معمولی واقعات ملتے ہیں. حضرت عمر رض نے اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو غزوہ بدر میں اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا کیونکہ وہ انہیں اپنی قوم کا فرد خیال نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عزوہ بدر میں اپنے بیٹے کو مبارزت کے لیے طلب کیا لیکن آپ ﷺ نے اپنی طبعی رحم دلی کے باعث اجازت نہ دی۔ اس سے بڑھ کر معاملہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا ہے جنہوں نے غزوہ
احد میں اپنے سگے باپ جراح کو قتل کیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے جس سے صرف نظر کیا جا سکے۔ تلوار چلی تھی اور باپ کے جسم پر وار ہوا تھا، اس باپ پر جو جنم دینے کا باعث تھا اور جس نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسے سے بڑھ کر کیا مثال مل سکتی ہے کہ ابتدائے اسلام کے دور میں نبی پاک ﷺ نے مسلمانوں کو قومیت سے متعلق کیا تصور دیا تھا۔
یہ سب واقعات نسل یا وطن کی بنیاد پر قومیت کا انکار کرتے ہیں اور دین و مذہب پر قوم کی بنیاد رکھنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب اگر عربوں، ترکوں یا کسی دوسری قوم کا طرز عمل مختلف ہو تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے دلیل تو رسول ﷺ کی مثال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے اسلام اور کفر کی تفریق میں جدا جدا ہو جائیں اور دو بالکل اجنبی آدمی اسلام میں متحد ہونے کی وجہ سے ایک قومیت میں مشترک ہوں۔
قائد اعظم کا اس بارے میں کیا موقف تھا وہ ان کے ایسوسی ایٹڈ پریس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویو سے ظاہر ہوتا ہے
The difference between the Hindus and Muslims is deep-rooted and ineradicable, we are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions, in short we have our own distinctive outlook on life and of life. By any canons of international law we are a nation.
[Interview to Preston Crom of Associated Press of America, Bombay, July 1, 1942, K.A.K Yusufi, edit, “Speeches, Statements and Messages of the Quaid-e-Azam”, Lahore, Bazm-e-Iqbal, 1996, Vol III, P. 1578]
”مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین اختلافات بہت وسیع اور گہرے ہیں۔ ہم ایک الگ قوم ہیں۔ ہماری اپنی تہذیب و تمدن ہے۔ زبان، ادب، رسوم و رواج، رکھ رکھاؤ، اخلاقیات، قوانین، تاریخ، تہوار، نام، مقاصد اور نظریات سب میں ہم ایک الگ اور نمایاں قوم ہیں۔ مختصرا یہ کہ ہم ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ کسی بھی بین الاقوامی قانون کے مطابق ہم ایک الگ قوم ہیں۔“
اقبال کا نظریہ بھی اس بارے میں نہایت واضح اور دو ٹوک ہے۔ فرماتے ہیں
قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں
جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں
بازو ترا توحید کی قوت کے قوی ہے
اسلام ترا دیس ہے تو مصطفی ہے
اقبال نے تو رنگ نسل زمین کا انکار کر کے خاص طور پر مذہب پر قومیت کی بنیاد رکھی ہے
بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا
نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی
اور دوسری جگہ کہا کہ
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم زبوں حالی کا شکار ہوتی ہے تو اس میں ایسے کم حوصلہ افراد کا پیدا ہو جانا بالکل فطری امر ہے جو اس قوم سے اپنی وابستگی پر شرمندگی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ماں اگر غریب یا بد صورت ہو تو اس سے قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان اگر پسماندگی اور انتشار کا شکار ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے اسے ہم نے ہی حل کرنا ہے۔ اس سے پریشان ہو کر قومیت سے ہی انکاری ہو جانا کوئی بہادری کی علامت نہیں۔ ہم سب ایک نبی کے ماننے والے ہیں اور اس نبی کی نام پر ہی اکٹھے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں اکٹھے کرنے والی نہیں ہے۔
اسلام قبائل کو محض تعارف کا سبب قرار دیتا ہے نہ کہ اس کی بنیاد پر قومیت الگ کرنے کا۔ جہاں تک موجودہ جدید ریاستوں کا تعلق ہے تو ان میں رہ کر بھی متحد رہا جا سکتا ہے۔ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یہ آج کے مسلمان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اگرچہ یہ منزل ایک طویل سفر کی متقاضی ہے مگر مقصود و مطلوب یہی ہے.
یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی
اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی
 ایک بھائی نے بھارت اور پاکستان کی حالیہ کشیدگی میں دونوں طرف کے مسلمانوں کا اپنے اپنے دیش کے حق میں دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنے سے دو قومی نظرئیے پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہوئے دو قومی نظریے کے مقابلے میں دی جانے والی اس تاریخی رائے کو وزنی قرار دیا ہے کہ ”قومیں وطن سے بنتی ہیں نہ کہ مذہب سے۔“ مگر یہ نتیجہ کچھ مزید غور و خوض کا متقاضی ہے۔
ایک بھائی نے بھارت اور پاکستان کی حالیہ کشیدگی میں دونوں طرف کے مسلمانوں کا اپنے اپنے دیش کے حق میں دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنے سے دو قومی نظرئیے پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہوئے دو قومی نظریے کے مقابلے میں دی جانے والی اس تاریخی رائے کو وزنی قرار دیا ہے کہ ”قومیں وطن سے بنتی ہیں نہ کہ مذہب سے۔“ مگر یہ نتیجہ کچھ مزید غور و خوض کا متقاضی ہے۔

 علمی ذوق رکھنے والے احباب نے یقینا ڈارون کے نظریہ ارتقا کے بارے میں سن رکھا ہو گا. نظریہ ارتقا دراصل ڈارون نہیں بلکہ جین بیپٹسٹ لمارک کا مرہون منّت ہے جو اس نے انیسویں صدی کے اوائل میں پیش کیا. ڈارون نے اس نظریہ کو اپنی تھیوری آف نیچرل سلیکشن کے ذریعے جلا بخشی اور وہ میکانزم بتایا جس کے نتیجے میں جاندار ارتقائی منازل طے کر کے مختلف انواع میں ظاہر ہوتے ہیں. مغربی ممالک میں اس نظریے کو سائنسدانوں اور عوام میں عمومی قبولیت کا درجہ حاصل ہے، ان ممالک میں ستر فیصد سے زیادہ عوام اس کی صحت کی قائل ہے. اس کے برعکس وہ ممالک جہاں روزمرّہ کی زندگی میں مذہبی رنگ آج بھی غالب ہے، اسے جھوٹ کا پلندہ سمجھا جاتا ہے، جو لوگوں کو مذہب سے دور کرنے اور انھیں ملحد بنانے کے لیے استمعال ہوتا ہے. میں یہاں اس نظریہ کی تفصیل میں جائے بغیر اس سائنسی اپروچ کی بات کروں گا جسے اپنا کر یہ نظریہ بآسانی سمجھا جا سکتا ہے.
علمی ذوق رکھنے والے احباب نے یقینا ڈارون کے نظریہ ارتقا کے بارے میں سن رکھا ہو گا. نظریہ ارتقا دراصل ڈارون نہیں بلکہ جین بیپٹسٹ لمارک کا مرہون منّت ہے جو اس نے انیسویں صدی کے اوائل میں پیش کیا. ڈارون نے اس نظریہ کو اپنی تھیوری آف نیچرل سلیکشن کے ذریعے جلا بخشی اور وہ میکانزم بتایا جس کے نتیجے میں جاندار ارتقائی منازل طے کر کے مختلف انواع میں ظاہر ہوتے ہیں. مغربی ممالک میں اس نظریے کو سائنسدانوں اور عوام میں عمومی قبولیت کا درجہ حاصل ہے، ان ممالک میں ستر فیصد سے زیادہ عوام اس کی صحت کی قائل ہے. اس کے برعکس وہ ممالک جہاں روزمرّہ کی زندگی میں مذہبی رنگ آج بھی غالب ہے، اسے جھوٹ کا پلندہ سمجھا جاتا ہے، جو لوگوں کو مذہب سے دور کرنے اور انھیں ملحد بنانے کے لیے استمعال ہوتا ہے. میں یہاں اس نظریہ کی تفصیل میں جائے بغیر اس سائنسی اپروچ کی بات کروں گا جسے اپنا کر یہ نظریہ بآسانی سمجھا جا سکتا ہے.
 15 ستمبر 2016 کو دلیل میں مجیب الحق حقی کی بگ بینگ کے حوالے سے ایک تحریر شائع ہوئی جس میں کافی ساری غلط فہمیاں اکٹھی کی گئی تھیں اور انتہائی سادہ سائنسی حقائق کو بھی درست بیان نہیں کیا گیا۔ بگ بینگ کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے غلط تصورات مقبول ہیں اور تحریر میں بھی انہی تصورات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ ان کی غلطیوں پر بحث کرنے کے بجائے میں نے مناسب سمجھا کہ بگ بینگ کے حوالے سے ایک مضمون تحریر کر لیا جائے جس میں ان غلطیوں پر بھی سیر حاصل بحث ہو جائے گی۔
15 ستمبر 2016 کو دلیل میں مجیب الحق حقی کی بگ بینگ کے حوالے سے ایک تحریر شائع ہوئی جس میں کافی ساری غلط فہمیاں اکٹھی کی گئی تھیں اور انتہائی سادہ سائنسی حقائق کو بھی درست بیان نہیں کیا گیا۔ بگ بینگ کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے غلط تصورات مقبول ہیں اور تحریر میں بھی انہی تصورات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ ان کی غلطیوں پر بحث کرنے کے بجائے میں نے مناسب سمجھا کہ بگ بینگ کے حوالے سے ایک مضمون تحریر کر لیا جائے جس میں ان غلطیوں پر بھی سیر حاصل بحث ہو جائے گی۔
 کانٹ کی معروف کتاب Religion within the limits of reason alone کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک مذہب کی وہی صورت قابل قبول ہے، جس میں کوئی چیز عقل سے ماورا نہ ہو۔ اس کا کہنا ہے کہ مذہب کی بنیاد عقل پر ہونی چاہیے نہ کہ وحی پر۔ وہ وحی کو ایک غیر یقینی ذریعہ علم قرار دیتاہے، جس پر معاملات کی بنیاد رکھنا گمراہی ہے۔ وحی آدمیوں کے پاس آدمیوں ہی کے ذریعے سے پہنچتی ہے، جن سے غلطی ہونا عین ممکن ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ آدمی کے پاس براہ راست خدا کی طرف سے آتی ہے، تو بھی آدمی کو اس کی تعبیر میں غلطی نہ لگنے کی کیا ضمانت ہے؟ حضرت ابراہیم کا خواب میں اپنے بیٹے کو بھیڑ کی طرح قربان کرنے کا حکم اسی قبیل سے ہے۔ایسی صورت میں بندہ انتہائی درجےکے غلط کام کا خطرہ مول لیتا ہے۔ آج کل کانٹ کے اس خیال کے حوالے سے اہل علم میں بحث جاری ہے۔
کانٹ کی معروف کتاب Religion within the limits of reason alone کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک مذہب کی وہی صورت قابل قبول ہے، جس میں کوئی چیز عقل سے ماورا نہ ہو۔ اس کا کہنا ہے کہ مذہب کی بنیاد عقل پر ہونی چاہیے نہ کہ وحی پر۔ وہ وحی کو ایک غیر یقینی ذریعہ علم قرار دیتاہے، جس پر معاملات کی بنیاد رکھنا گمراہی ہے۔ وحی آدمیوں کے پاس آدمیوں ہی کے ذریعے سے پہنچتی ہے، جن سے غلطی ہونا عین ممکن ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ آدمی کے پاس براہ راست خدا کی طرف سے آتی ہے، تو بھی آدمی کو اس کی تعبیر میں غلطی نہ لگنے کی کیا ضمانت ہے؟ حضرت ابراہیم کا خواب میں اپنے بیٹے کو بھیڑ کی طرح قربان کرنے کا حکم اسی قبیل سے ہے۔ایسی صورت میں بندہ انتہائی درجےکے غلط کام کا خطرہ مول لیتا ہے۔ آج کل کانٹ کے اس خیال کے حوالے سے اہل علم میں بحث جاری ہے۔
 اکثر یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے کہ قوم کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ قوم کسی خطے میں رہنے والے افراد سے مل کر بنتی ہے یا ایک زبان بولنے والے مل کر ایک قوم بناتے ہیں؟ ایک رنگ کے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں یا مشترک مفاد کے حامل لوگ ایک قوم کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں؟ بھانت بھانت کا فلسفہ سننے کو ملتا ہے۔ لبرل اور سیکولر خواتین و حضرات مصر ہیں کہ ایک خطے میں رہنے والے اور مشترک تاریخ و تمدن رکھنے والے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں۔ پھر قوم، ملت اور امت کے الفاظ کی بھی تشریح کی جاتی ہے اور ان میں فرق بیان کیے جاتے ہیں۔
اکثر یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے کہ قوم کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ قوم کسی خطے میں رہنے والے افراد سے مل کر بنتی ہے یا ایک زبان بولنے والے مل کر ایک قوم بناتے ہیں؟ ایک رنگ کے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں یا مشترک مفاد کے حامل لوگ ایک قوم کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں؟ بھانت بھانت کا فلسفہ سننے کو ملتا ہے۔ لبرل اور سیکولر خواتین و حضرات مصر ہیں کہ ایک خطے میں رہنے والے اور مشترک تاریخ و تمدن رکھنے والے لوگ ایک قوم ہوتے ہیں۔ پھر قوم، ملت اور امت کے الفاظ کی بھی تشریح کی جاتی ہے اور ان میں فرق بیان کیے جاتے ہیں۔

 جب شناختی کارڈ اور پاسپورٹ فارمز میں مذہب کا خانہ بنایا گیا تھا تو اس پر کافی شور اٹھا تھا۔ ہمارے لبرل بھائیوں کا موقف تھا کہ چونکہ مذہب، فرد کا نجی معاملہ ہوتا ہے لہٰذا اس کے بارے میں ریاست کون ہوتی ہے کسی سے اس کا مذہب معلوم کرنے والی؟
جب شناختی کارڈ اور پاسپورٹ فارمز میں مذہب کا خانہ بنایا گیا تھا تو اس پر کافی شور اٹھا تھا۔ ہمارے لبرل بھائیوں کا موقف تھا کہ چونکہ مذہب، فرد کا نجی معاملہ ہوتا ہے لہٰذا اس کے بارے میں ریاست کون ہوتی ہے کسی سے اس کا مذہب معلوم کرنے والی؟


 فیس بک پر محترم رعایت اللہ فاروقی صاحب ان معدودے چند اصحاب میں سے ہیں جنہیں میں اپنے اساتذہ میں شمار کرتا ہوں، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میری تلخ نوائیوں اور احمقانہ سوالات کے باوجود فاروقی صاحب نے ہمیشہ شفقت فرمائی. جو لوگ فاروقی صاحب کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ فاروقی صاحب کی ہر تحریر کے پیچھے ایک ہی جذبہ کارفرما ہوتا ہے اور وہ ہے نوجوان نسل کی بالعموم اور مدارس کے طلبہ کی بالخصوص تربیت. میرے اپنے طلبہ اور عزیز جب مجھ سے کچھ پڑھنے کے بارے مشورہ طلب کرتے ہیں تو دیگر باتوں کے علاوہ میں انہیں فیس بک پر فاروقی صاحب، ڈاکٹر عاصم اللہ بخش، عامر خاکوانی، قاری حنیف ڈار، فرنود عالم اور محمد اشفاق کو پڑھنے اور فالوو کرنے کا مشورہ دیتا ہوں.
فیس بک پر محترم رعایت اللہ فاروقی صاحب ان معدودے چند اصحاب میں سے ہیں جنہیں میں اپنے اساتذہ میں شمار کرتا ہوں، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میری تلخ نوائیوں اور احمقانہ سوالات کے باوجود فاروقی صاحب نے ہمیشہ شفقت فرمائی. جو لوگ فاروقی صاحب کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ فاروقی صاحب کی ہر تحریر کے پیچھے ایک ہی جذبہ کارفرما ہوتا ہے اور وہ ہے نوجوان نسل کی بالعموم اور مدارس کے طلبہ کی بالخصوص تربیت. میرے اپنے طلبہ اور عزیز جب مجھ سے کچھ پڑھنے کے بارے مشورہ طلب کرتے ہیں تو دیگر باتوں کے علاوہ میں انہیں فیس بک پر فاروقی صاحب، ڈاکٹر عاصم اللہ بخش، عامر خاکوانی، قاری حنیف ڈار، فرنود عالم اور محمد اشفاق کو پڑھنے اور فالوو کرنے کا مشورہ دیتا ہوں.
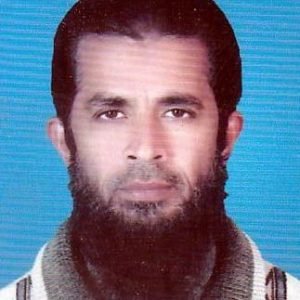 مغربی دنیا گزشتہ پانچ سو سال سے چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ مذہب کا ریاست و سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا ریاست و سیاست کی تشکیل میں مذہب کو کوئی کردار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ نظریہ جدید دنیا کی عالمی طاقتوں کا ایک متفقہ عقیدہ بن چکا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرچکے ہیں کہ کسی بھی ملک پر مذہبی قوانین کی بالادستی کسی صورت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ جدید دنیا کے اس عقیدے کے آگے سارے مذاہب نے سرجھکادیا اور جدید دنیا کا یہ فیصلہ قبول کرلیا، سوائے اسلام کے۔ چنانچہ جدید دنیا نے فیصلہ کیا کہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں کسی بھی ملک کی سیاسی و ریاستی تشکیل برداشت نہیں کی جائے گی۔ مغربی دنیا کے اسی جبر اور استبداد کا اظہار ہمیں الجزائر، مصر، ترکی اور افغانستان میں نظر آتا ہے کہ ان ملکوں میں جب جب اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل کرنے کی کوشش کی گئی، مغربی دنیا نے اپنے درندوں کو ان ملکوں پر چڑھا دوڑایا۔
مغربی دنیا گزشتہ پانچ سو سال سے چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ مذہب کا ریاست و سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا ریاست و سیاست کی تشکیل میں مذہب کو کوئی کردار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ نظریہ جدید دنیا کی عالمی طاقتوں کا ایک متفقہ عقیدہ بن چکا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرچکے ہیں کہ کسی بھی ملک پر مذہبی قوانین کی بالادستی کسی صورت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ جدید دنیا کے اس عقیدے کے آگے سارے مذاہب نے سرجھکادیا اور جدید دنیا کا یہ فیصلہ قبول کرلیا، سوائے اسلام کے۔ چنانچہ جدید دنیا نے فیصلہ کیا کہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں کسی بھی ملک کی سیاسی و ریاستی تشکیل برداشت نہیں کی جائے گی۔ مغربی دنیا کے اسی جبر اور استبداد کا اظہار ہمیں الجزائر، مصر، ترکی اور افغانستان میں نظر آتا ہے کہ ان ملکوں میں جب جب اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل کرنے کی کوشش کی گئی، مغربی دنیا نے اپنے درندوں کو ان ملکوں پر چڑھا دوڑایا۔