 1492ء کا سال اسلامی تاریخ کا انتہائی بدقسمت سال تھا کیونکہ اسی سال اندلس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر انتہا پسند عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا. میں جب بھی تاریخ اندلس کا تنقیدی مطالعہ کرتا تو ایک سوال پوری شدت کے ساتھ ذہن میں ابھرتا تھا کہ آٹھ سو سال تک اس سرزمین پر حکومت کرنے کے باوجود وہ کون سی وجوہات تھیں کہ نہ صرف وہاں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوگئی بلکہ مسلمانوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا؟
1492ء کا سال اسلامی تاریخ کا انتہائی بدقسمت سال تھا کیونکہ اسی سال اندلس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر انتہا پسند عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا. میں جب بھی تاریخ اندلس کا تنقیدی مطالعہ کرتا تو ایک سوال پوری شدت کے ساتھ ذہن میں ابھرتا تھا کہ آٹھ سو سال تک اس سرزمین پر حکومت کرنے کے باوجود وہ کون سی وجوہات تھیں کہ نہ صرف وہاں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوگئی بلکہ مسلمانوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا؟
دیگر سیاسی و جنگی وجوہات کے ساتھ جو چیز میری سمجھ میں آ سکی وہ ہے مسلمانوں (خواہ وہ حکمران ہوں یا عوام) کی دعوت الی اللہ سے غفلت. ظاہر ہے کہ مسلمان اللہ کے اس فرمان ’لا اکراہ فی الدین‘ یعنی’دین میں کوئی جبر نہیں‘ کا پابند ہے لیکن اندلس کے مسلمان بدقسمتی سے اللہ کا دوسرا فرمان ’كنتم خير امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنھون عن المنكر‘ یعنی ’اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کےلیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو‘ کو بھول گئے اور مقامی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور اسلام کے مطابق ان کی تربیت و تہذیب کرنے میں ناکام رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سیاسی اور پھر جنگی آویزش شروع ہوئی تو پورا اندلس کم و بیش انتہا پسند عیسائی جنگجوؤں کے ساتھ کھڑا تھا اور مسلمان دوسری طرف اکیلے کھڑے تھے جو خود یا جن کے آباؤ اجداد شمالی افریقہ سے یہاں آئے تھے یعنی آٹھ سو سال بعد بھی مسلمان سرزمین اندلس پر اجنبی ہی سمجھے جاتے تھے.
اس تاریخی مطالعے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب کوئی دس سال پہلے اللہ نے چین میں آنے اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنے کا موقع عطا کیا تھا تو خواہش تھی کہ جیسے اور جتنا ممکن ہو سکے، دین حق کی دعوت کا ابلاغ کیا جائے. اس سلسلے میں، میں نے ممکن حد تک کوشش کی کہ چین میں مقیم دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر دعوت کا کام کیا جائے. کچھ نے اتفاق کیا تو کچھ نے اختلاف اور کسی نے مخالفت بھی کی اور کسی نے ڈرایا بھی کہ ’’یہ چین ہے بھائی، احتیاط کرو‘‘ نہیں معلوم کہ کیوں کچھ لوگوں کو دنیا کماتے وقت تو ’احتیاط‘ اور ’اعتدال‘ کے الفاظ یاد نہیں رہتے، مگر دین کے وقت سب یاد آ جاتا ہے.
خیر اللہ کا نام لے کر اپنے کچھ چینی اور کچھ غیر چینی دوستوں کے ساتھ مل کر دعوت دین کی بنیاد رکھی. اصل ہدف مقامی چینی مسلمان اور ان کی اولادیں تھیں. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس کام میں برکت عطا کی اور نہ صرف بےشمار چینی نسلی مسلمان واپس اسلام کی طرف لوٹے بلکہ بہت سے غیر مسلم چینیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے حالانکہ میں نے 2008ء کے شروع میں چین چھوڑ دیا تھا. 2011 میں جب دوبارہ یہاں آیا تو یہ دیکھ کر خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ لوگ اسی طرح متحرک اور دعوت کا کام کر رہے تھے.
اس بار مسلمانوں کے بجائے براہ راست غیر مسلموں کے ساتھ مکالمہ شروع کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ چینی نسل کے لوگ اسلام کو سمجھیں اور اللہ اگر توفیق دے تو اسے قبول بھی کریں. عوام کو دعوت دینے اور اعلی تعلیم یافتہ طبقے کے ساتھ مکالمہ میں کافی فرق ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں، لیکن اس کام کا بھی فائدہ ہوا. لوگوں تک درست پیغام درست طریقے سے پہنچانے کے لیے خود بھی اچھی خاصی تیاری کرنی پڑتی ہے جس سے اپنا مطالعہ وسیع ہوتا ہے. میری دعوت کا اصل میدان میرا اپنا آفس ہے. یہاں پیشہ وارانہ معاملات میں اعلی کارکردگی کو دعوت کو بنیاد بنانا پڑتا ہے کیونکہ اگر پیشہ وارانہ معاملات میں کمزوری ہو تو اپنے کیریئر کو نقصان ہو نہ ہو’ دعوت دین کا نقصان بہرحال ہوتا ہے کہ پھر ایسے بندے کی باتوں کو لوگ اہمیت نہیں دیتے. ظاہر ہے پیشہ وارانہ ذمہ داری ٹھیک طرح سے ادا نہ کی جائے تو نہ صرف یہ کہ رزق مشکوک ہو جاتا ہے بلکہ انسان کی شخصیت کو بھی دھندلا جاتی ہے. اللہ ہمیں اس خرابی سے بچائے. آمین. شعوری طور پر کوشش کی کہ میرے کولیگز مذہب کو زیر بحث لائیں،گاہے اس میں کامیابی ہوتی ہے اور گاہے ناکامی لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ ان کے مذپب بالخصوص اسلام کے بارے میں سوالات اٹھانے سے مجھے اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریبا تمام کولیگز کو اسلام کا ابتدائی تعارف ضرور حاصل ہو چکا ہے. ایک کولیگ آج کل چینیوں کو اسلام سے متعارف کروانے کے لیے بلاگ بھی لکھ رہا ہے. اللہ میرے حال پر بھی رحم کرے اور ان کو بھی اسلام کی نعمت عطا فرمائے. آمین
چینی اکثر مسئلہ غلامی، عورتوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات، جہاد اور دور جدید میں اسلام کے قابل عمل ہونے پر سوال اٹھاتے ہیں. سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے: ’’ہم نے سنا ہے کہ مسلمان کئی کئی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں‘‘. یہ سنتے ہی میں اکثر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتا ہوں. بہرحال اپنی سی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو درست معلومات پہنچائی جائیں. ویسے میں نے جب ان کو عورت کے معاملات کے بارے میں قرآن کی تعلیمات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی وضاحت کی تو میری فی میل کولیگز حیران اور خوشی سے اچھل پڑیں اور کہنے لگیں کہ:’’ہم بھی مسلمان ہونا چاہتی ہیں‘‘ تاہم ایک خالص مادیت پرست معاشرے میں ایسے جذبات زیادہ دیر تک برقرار رہنا کافی مشکل ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ جذبات مستقل شکل اختیار کر لیں.
چین میں سید مودودی، سید قطب اور محمد قطب کی کتابیں بالکل شروع میں ہی ترجمہ ہو گئی تھیں اور سید مودودی کا ’’مقدمہ تفہیم القرآن‘‘ جیبی سائز کے ترجمہ قرآن کے شروع میں لگا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح خطبات اور دینیات وسیع پیمانے پر چھپتی اورپڑھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یوسف القرضاوی کی کتب اور مولانا زکریا کی فضائل اعمال کے ترجمے بھی دستیاب ہیں، تاہم چونکہ اکثر ترجمے کافی عرصہ پہلے ہوئے تھے اور اب جبکہ چینی زبان میں کافی تبدیلیاں ہو چکی ہیں لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کتابوں کے جدید چینی زبان میں ترجمے تیار کیے جائیں. نیت ہو تو اللہ راستے بھی بنا دیتا ہے، دوستوں کےلیے خوشخبری کہ اس کا راستہ بن چکا ہے، اور سفر جاری ہے-
اس ساری کوشش کا مقصد یہ ہے کہ چین مستقبل قریب کی معاشی اور فوجی سپر پاور نہیں بلکہ شاید میگا پاور بن رہا ہے. اس ملک میں جس نظریے کے ماننے والے جتنے زیادہ اور جتنے طاقتور ہوں گے، اتنا ہی اس نظریے اور اس کے حاملین کے لیے بہتر ہوگا. اور جس نظریے کے اثرات کم ہوں گے، اس کے حاملین کے لیے کوئی اچھا منظر شاید نہیں بن سکے گا. یہاں لاکھوں غیر ملکی مسلمان آتے ہیں، پڑھتے، کام اور کاروبار کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے اکثریت نے جلد یا بدیر اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہی جانا ہوتا ہے. یہاں رہنا چینیوں نے ہی ہے لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اندلس سے سبق سیکھیں اور میدان عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے خالی نہ چھوڑیں جو پوری قوت اور وسائل کے ساتھ چینیوں کو اپنے اپنے مذہب کے کی طرف لے جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں.
میرے جیسے گناہگار ایسی ہی کوشش میں اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش میں مصروف مصروف ہیں. اللہ جانتا ہے. اللہ ہی تو جانتا ہے.







 نیشنلزم کےنام پر لوگوں کو دیے جانے والے دھوکوں میں سب سے اہم دھوکہ یہ نعرہ ہے کہ قومیں وطن سے تشکیل پاتی ہیں۔ لیکن تقدیر نے ان لوگوں کے منہ پر طمانچہ مارنےکے لیے روز اول سے ہی الٹا کھیل کھیلا ہے۔ انسان کی 5 ہزار سالہ معلوم تاریخ میں یہ رشتہ اتنا کمزور رہا ہے کہ جب زمین کے ایک ٹکرے نے چارہ اگلنا بند کیا تو انسانوں نے اپنی اس ماں کو خیرباد کہا، بوریا بستر اٹھایا اور نیا وطن بنا لیا۔
نیشنلزم کےنام پر لوگوں کو دیے جانے والے دھوکوں میں سب سے اہم دھوکہ یہ نعرہ ہے کہ قومیں وطن سے تشکیل پاتی ہیں۔ لیکن تقدیر نے ان لوگوں کے منہ پر طمانچہ مارنےکے لیے روز اول سے ہی الٹا کھیل کھیلا ہے۔ انسان کی 5 ہزار سالہ معلوم تاریخ میں یہ رشتہ اتنا کمزور رہا ہے کہ جب زمین کے ایک ٹکرے نے چارہ اگلنا بند کیا تو انسانوں نے اپنی اس ماں کو خیرباد کہا، بوریا بستر اٹھایا اور نیا وطن بنا لیا۔
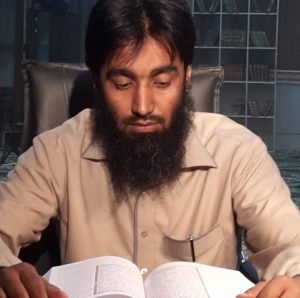 اب کے کوئٹہ لہولہان ہو گیا ہے۔ کوئٹہ پاکستان ہی نہیں، وہ زیادہ پاکستان ہے۔ جسم کا جو حصہ زیادہ زخم خوردہ ہو، اسے زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ابھی ابھی میں نے انگوٹھے کے ناخن کے زخم کی اذیت سے شفا پائی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ ادھر کوئی بچہ میری جانب لپکتا، ادھر میں پاؤں سمیٹ لیتا۔ لپکتا کیا کوئی ہلتا بھی تو میرا لاشعور از خود میرے پاؤں کو محتاط اور متحرک کر دیتا۔ کوئٹہ ہو یا کے پی کے اور سندھ، کسی وجہ سے وہ پنجاب کے بارے میں اسی شعوری اور لاشعوری احتیاط میں ہیں۔ یہ سٹریٹیجک اعتبار اور سیاسی حیثیت سے بھی زیادہ حساس صوبے ہیں۔ کچھ دشمن نے اور کچھ نادان سیاسی دوستوں نے یہاں کے زخموں کی دانستہ مسیحائی کی کوشش نہیں کی۔ دشمن کا تو خیر سے دشمنی کا میدان اور ہماری اذیت کا مقام ہی یہ صوبے ہوگئے، مگر نادان دوستوں نے بھی وقتی سیاسی مفاد کے لیے انھیں گردن دبوچنے کا پریشر پوائنٹ سمجھ کے ہر آن برتا ہے۔ یہ چیزیں معروف اور معلوم ہیں۔ میں صرف اپنے درد کی شدت کے اظہار کے لیے دہرا رہا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جسدِ وطن کے نسبتا اس حساس حصے پر چوٹ لگنے سے میرے دل، میرے دماغ اور میرے دورانِ خون پر کچھ زیادہ ہی اثر ہوا ہے۔گو میں کوئٹہ ابھی تک نہیں گیا، وہاں لہو میں ڈوبنے والوں میں کوئی میرا شناسا بھی نہ تھا مگر یہ جو پاکستان پر، انسان پر اور میرے ہم ایمان پر وارہوا ہے تو میرا جگر ہی کٹ اور میرا بدن ہی بٹ گیا ہے۔ میرا درد اس لیے بھی سوا ہے کہ یہ کہاں اور کس سنگدلی سے وار کیا گیا۔زخم پر نمک چھڑکنے کا محاورہ ماند ہوگیا، یہ انسانی شکار کے ہانکے کی بدترین مثال ہے۔ پہلے بارود کی بوچھاڑ سے زخمیوں کا ہانکا کیا گیا اور پھر شفاخانے میں پڑے زخمیوں کے زخموں پر خود کش بارود چھڑکا گیا۔ ابھی ابھی دلیل پر برادرم آصف محمود کا نوحہ اور اس سے پہلے ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کا تجزیہ پڑھا ہے۔ میں برادرِ اکبر آصف محمود کے الم اور جناب عاصم اللہ بخش کی دانش، ہر دو پر صاد اور ہر دو کی تائید کرتا ہوں۔ ان کی ہاں میں ہاں اور ان کے درد میں اپنا درد ملاتاہوں۔
اب کے کوئٹہ لہولہان ہو گیا ہے۔ کوئٹہ پاکستان ہی نہیں، وہ زیادہ پاکستان ہے۔ جسم کا جو حصہ زیادہ زخم خوردہ ہو، اسے زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ابھی ابھی میں نے انگوٹھے کے ناخن کے زخم کی اذیت سے شفا پائی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ ادھر کوئی بچہ میری جانب لپکتا، ادھر میں پاؤں سمیٹ لیتا۔ لپکتا کیا کوئی ہلتا بھی تو میرا لاشعور از خود میرے پاؤں کو محتاط اور متحرک کر دیتا۔ کوئٹہ ہو یا کے پی کے اور سندھ، کسی وجہ سے وہ پنجاب کے بارے میں اسی شعوری اور لاشعوری احتیاط میں ہیں۔ یہ سٹریٹیجک اعتبار اور سیاسی حیثیت سے بھی زیادہ حساس صوبے ہیں۔ کچھ دشمن نے اور کچھ نادان سیاسی دوستوں نے یہاں کے زخموں کی دانستہ مسیحائی کی کوشش نہیں کی۔ دشمن کا تو خیر سے دشمنی کا میدان اور ہماری اذیت کا مقام ہی یہ صوبے ہوگئے، مگر نادان دوستوں نے بھی وقتی سیاسی مفاد کے لیے انھیں گردن دبوچنے کا پریشر پوائنٹ سمجھ کے ہر آن برتا ہے۔ یہ چیزیں معروف اور معلوم ہیں۔ میں صرف اپنے درد کی شدت کے اظہار کے لیے دہرا رہا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جسدِ وطن کے نسبتا اس حساس حصے پر چوٹ لگنے سے میرے دل، میرے دماغ اور میرے دورانِ خون پر کچھ زیادہ ہی اثر ہوا ہے۔گو میں کوئٹہ ابھی تک نہیں گیا، وہاں لہو میں ڈوبنے والوں میں کوئی میرا شناسا بھی نہ تھا مگر یہ جو پاکستان پر، انسان پر اور میرے ہم ایمان پر وارہوا ہے تو میرا جگر ہی کٹ اور میرا بدن ہی بٹ گیا ہے۔ میرا درد اس لیے بھی سوا ہے کہ یہ کہاں اور کس سنگدلی سے وار کیا گیا۔زخم پر نمک چھڑکنے کا محاورہ ماند ہوگیا، یہ انسانی شکار کے ہانکے کی بدترین مثال ہے۔ پہلے بارود کی بوچھاڑ سے زخمیوں کا ہانکا کیا گیا اور پھر شفاخانے میں پڑے زخمیوں کے زخموں پر خود کش بارود چھڑکا گیا۔ ابھی ابھی دلیل پر برادرم آصف محمود کا نوحہ اور اس سے پہلے ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کا تجزیہ پڑھا ہے۔ میں برادرِ اکبر آصف محمود کے الم اور جناب عاصم اللہ بخش کی دانش، ہر دو پر صاد اور ہر دو کی تائید کرتا ہوں۔ ان کی ہاں میں ہاں اور ان کے درد میں اپنا درد ملاتاہوں۔
 چرچل کا قول ہے کہ امریکن صحیح کام اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس کرنے کو کوئی غلط کام نہیں ہوتا۔ مذکورہ قول کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہم پاکستانی بھی امریکنز سے کسی طرح پیچھے نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ غلط وقت پر صحیح کام اور صحیح وقت پر غلط کام کرنے کے عادی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے اندر پائے جانے والے وہ تین جنون ہیں جن کا عشر عشیر بھی کسی دوسری قوم میں نہیں ملتا۔
چرچل کا قول ہے کہ امریکن صحیح کام اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس کرنے کو کوئی غلط کام نہیں ہوتا۔ مذکورہ قول کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہم پاکستانی بھی امریکنز سے کسی طرح پیچھے نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ غلط وقت پر صحیح کام اور صحیح وقت پر غلط کام کرنے کے عادی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے اندر پائے جانے والے وہ تین جنون ہیں جن کا عشر عشیر بھی کسی دوسری قوم میں نہیں ملتا۔

 جمہوریت کو ’’حاکمیت عوام’’ کے نظریے کی بنیاد پر کفریہ نظام قرار دینے اور حاکمیت عوام کو اس کا جزو لاینفک قرار دینے والے گروہ کی طرف سے ایک عامۃ الورود اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جمہوریت میں اگر دستوری طور پر قرآن وسنت کی پابندی قبول کی جاتی ہے تو اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ خدا کا حکم ہے جس کی اطاعت لازم ہے، بلکہ اس اصول پر کی جاتی ہے کہ یہ اکثریت نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے اور وہ جب چاہے، اس پابندی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے دستور میں اس کی تصریح کے باوجود جمہوریت درحقیقت ”حاکمیت عوام“ ہی کے فلسفے پر مبنی نظام ہے۔
جمہوریت کو ’’حاکمیت عوام’’ کے نظریے کی بنیاد پر کفریہ نظام قرار دینے اور حاکمیت عوام کو اس کا جزو لاینفک قرار دینے والے گروہ کی طرف سے ایک عامۃ الورود اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جمہوریت میں اگر دستوری طور پر قرآن وسنت کی پابندی قبول کی جاتی ہے تو اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ خدا کا حکم ہے جس کی اطاعت لازم ہے، بلکہ اس اصول پر کی جاتی ہے کہ یہ اکثریت نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے اور وہ جب چاہے، اس پابندی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے دستور میں اس کی تصریح کے باوجود جمہوریت درحقیقت ”حاکمیت عوام“ ہی کے فلسفے پر مبنی نظام ہے۔