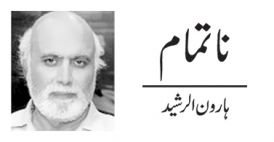
ساری بات احساس کی ہوتی ہے خود پسندی‘ تنگ نظری او ر مفاد پرستی کے سبب‘ دل اگر پتھر نہ ہو جائیں تو ناکامی بھی سازگار ہوتی ہے۔ اصلاح اور کامیابی کا راستہ کھول سکتی ہے۔
احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے
کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی
پنجاب میں ترقیاتی منصوبے کس بچگانہ ذہنیت کے ساتھ بروئے کار آتے ہیں‘ اس کی ایک مثال جناب شہباز شریف کی اورنج ٹرین ہے۔ مشرف دور میں وزیراعلیٰ چوہدری پرویز الٰہی کی حکومت نے 2004ء میں اس پر کام کا آغاز کیا۔ برسوں تک تحقیق و تدوین اور ماہرین سے مشوروں کا سلسلہ جاری رہا۔ آٹھ سال میں اسے مکمل ہونا تھا۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سرکاری خزانے سے ایک روپیہ بھی اس پر خرچ نہ ہوتا اور زِر تلافی کی مد میںہرگز کوئی ادائیگی نہ کرنا پڑتی۔
ایشیائی ترقیاتی بینک نے اس کے لیے قرض کی منظوری دے دی تھی جس کی شرح سود 0.25 فیصد سالانہ تھی۔ شہباز شریف حکومت نے چین سے جو قرض لیا ہے‘ اگرچہ اس کی شرائط بھی نرم ہیں؛ تاہم اس سے سات گنا زیادہ‘2.75 فیصد سالانہ۔ چوہدری پرویز الٰہی کے دور میں مرتب کیا جانے والا منصوبہ بنیادی طور پر ”بنائو چلائو اور حوالے کرو ‘‘کی بنیاد پر تھا‘ تکنیکی اصطلاح میں جسے B.O.Tکہا جاتا ہے۔
اگر اس پر عمل درآمد ہوتا تو 2012 ء میں یہ مکمل ہو جاتا۔کسی شورو غوغا کے بغیر‘ شریف خاندان کے روایتی دعووں اور قوم پر احسان جتلائے بغیر‘ نہ صرف یہ کہ سالانہ 16 ارب روپے کی زرِتلافی کی بچت ہوتی بلکہ قدیم تاریخی عمارات کو بھی خطرہ لاحق نہ ہوتا۔ جس کی بنا پر لاہور ہائی کورٹ نے تازہ حکم جاری کیا ہے۔ اس حکم کے تحت شالیمار باغ اور چوبرجی سمیت گیارہ تاریخی مقامات کے بارے میں یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ اورنج ٹرین کا ڈھانچہ کم از کم 200فٹ کے فاصلے پر ہو۔چوہدری پرویز الٰہی سے کل میں نے ایک طویل ملاقات کی۔ اپنا مؤقف انہوں نے تحریری طور پر بیان کیا‘ جس کے کچھ نکات درج ذیل ہیں۔
”ہمارے دور میں طے کردہ پراجیکٹ 97 کلومیٹر کا اور 4 لائنوں پر مشتمل تھا‘ اور اس کا بیشتر حصہ زیر زمین تھا۔ اس اہتمام کے ساتھ کہ اگر وہ کسی سرکاری عمارت یا ذاتی گھر کے نیچے سے گزرے تو وائبریشن سے ایک ذرا سا نقصان بھی اسے نہ پہنچے۔ پہلے مرحلے کا نام گرین لائن تھا اور یہ 27 کلومیٹر طویل ہوتا۔ 10 اوور ہیڈ برج‘ 12 انڈر پاس‘ 22مقامی ریلوے سٹیشن اس میں شامل تھے۔ خواتین اور بچوں کے حصے الگ رکھے گئے تھے۔ ایک گھنٹے میں 35 ہزار مسافروں کی گنجائش تھی۔ 4 لائنیں مکمل ہونے پر ایک گھنٹے میں 1 لاکھ 40 ہزارافراد شہر کے مختلف کونوں سے اپنی منزل تک جا سکتے۔ ہر 2 اور 5 منٹ کے بعد روانگی۔یعنی اگر کسی سے ایک گاڑی چھوٹ گئی تو 2 سے 5 منٹ کے درمیان وہ دوسری ٹرین پکڑ سکتا تھا۔ اوقات‘ صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک‘ کرایہ صرف 24 روپے رکھا گیا تھا۔ اس کے باوجود قطعاً کوئی خسارہ نہ ہوتا۔ اس لیے کہ بہترین کمپنیوں کا انتخاب کیا گیا اور پوری طرح یہ شفاف تھا۔
شہبازشریف نے اورنج لائن کی تعمیر کا ٹھیکہ ایک ایسی کمپنی‘ Norinco کو دیا ہے‘ بنیادی طور پر جو اسلحہ ساز کمپنی ہے۔ ہم نے Systra کمپنی کو سونپاتھا‘ جو کرتی ہی ”ماس ٹرین پراجیکٹ‘‘ ہے۔ چین کے ایک بڑے شہر شنگھائی سمیت دنیا کے تمام بڑے ماس ٹرانزٹ پراجیکٹ Systraکمپنی نے مکمل کیے ہیں۔ دونوں کمپنیوں کی ویب سائٹس پر جا کر آپ دونوں کی Specialization کو چیک کر سکتے ہیں۔
ہمارا پراجیکٹ زیر زمین تھا‘ لہٰذا اس سے لاہور کے تاریخی حسن میں اضافہ ہوتا۔ شہبازشریف کے پراجیکٹ سے لاہور اپنے تاریخی ورثہ سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو سکتا ہے۔ ہم نے آرکایالوجی ڈیپارٹمنٹ کو ہر مرحلے پر مشاورت میں شامل رکھا‘ اس دور کے آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر اوریا مقبول جان سے اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے‘ جو اب ایک آزاد اخبار نویس ہیں۔ انہوں نے اخبار میں اس موضوع پر لکھا بھی ہے۔غیر جانبدار آدمی کی شہادت ہمارے حق میںہے۔ نوازشریف حکومت تو بی جے پی سے بھی گئی گزری ہے۔
دلی میں ماس ٹرانزٹ منصوبہ شروع کرتے وقت بی جے پی نے مسلمانوں کے تاریخی ورثہ سے وہ سلوک نہیں کیا‘ جس طرح کا سلوک (نون) لیگ لاہور میں مسلمانوں کی تاریخی عمارات سے کر رہی ہے۔ ماس ٹرانزٹ پراجیکٹ ہمارا منصوبہ تھا۔ شہبازشریف نے اس کی نقل کرنے کی کوشش تو کی‘ لیکن عقل کے استعمال سے گریز ہی کیا‘ جیسا کہ ان کا شیوہ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس پراجیکٹ سے پنجاب کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے پراجیکٹ کی فی کلومیٹر لاگت‘ موجودہ پراجیکٹ سے بہت کم تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا منصوبہ تقریباً مفت تھا۔ جو ٹیکنالوجی اب استعمال کی جا رہی ہے‘ ہم اس سے بہتر ٹیکنالوجی استعمال کر رہے تھے۔ ہم نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے جو 1 ارب ڈالر منظور کرایا تھا‘ اس پر مارک اپ نہ ہونے کے برابرتھا‘ یعنی 0.25فیصد ۔
شہبازشریف نے برسر اقتدار آتے ہی میری مخالفت کی بنا پر اس بینک کو خط لکھا کہ پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے حالات سازگار نہیں۔ شہبازشریف کے اس خط کے جواب میں 4 جون 2008ء کوانہوں نے منظور شدہ قرضہ منسوخ کر دیا۔کیا کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ حرکت انہوں نے کیوں کی؟
ہمارا منصوبہ منافع بخش تھا اور سبسڈی کے بغیر بھی۔ جبکہ شہبازشریف کا پراجیکٹ سراسر خسارے کا ہے۔ لاہور اور راولپنڈی میں جنگلہ بس پر سالانہ 24 ارب روپے کا زرِ تلافی دیاجا رہا ہے‘ یعنی 2 ارب روپے ماہانہ‘ اورنج لائن ٹرین پر سالانہ سبسڈی کا کم از کم تخمینہ 16 ارب روپے ہے‘ یعنی سوا ارب روپے ماہانہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگلہ بس کے بعد اورنج لائن شروع کر کے پنجاب پر ایک اور سفید ہاتھی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ پنجاب کی آئندہ نسلوں کو بھی قرضے میں جکڑ دینے کا منصوبہ ہے۔ اپنا کمیشن وصول کر کے رفوچکر ہو جائیں گے‘ عوام مدتوں تک بھگتتے رہیں۔
اس منصوبے کے تحت تیز رفتار زیر زمین ٹرین نے کاہنہ سے چل کر جنرل ہسپتال‘ قینچی‘ کلمہ چوک‘ اچھرہ‘ مزنگ‘ کوئنز روڈ‘ ریگل چوک‘ جی پی او‘ داتا دربار‘ مینار پاکستان اور ٹمبر مارکیٹ سٹیشنوں پر رکتے ہوئے شاہدرہ تک کا فاصلہ کم سے کم وقت میں طے کرنا تھا۔ عوام کو انتہائی جدید اور محفوظ سفر کی سستی سہولت فراہم کی جانی تھیں۔ میٹرو ٹرین سسٹم تعمیرات کو مسمار‘ کاروباری مراکز کو تباہ اور ٹریفک مشکلات میں اضافہ کیے بغیر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زیر زمین تعمیر کیا جانا تھا۔ میٹرو ٹرین سسٹم کے22سٹیشنز میں کاروباری مراکز کی تعمیر سے عوام کو کاروبار کے نئے مواقع فراہم ہونے تھے۔ لاہور میں 10ارب ڈالر کی براہِ راست بیرونی سرمایہ کاری ہونا تھی۔ پنجاب کے عوام کو تقریباً1ارب روپے سالانہ کی بچت ہونا تھی۔ مگر افسوس پنجاب کو اس سرمایہ کاری سے محروم کر دیا گیا۔ لاہور کے تاریخی جمال‘ ہزاروں تاجروں کے کاروبار‘ تعمیرات اور مذہبی مقامات کو تباہ کر کے چند بسوں کے لیے سڑکوں کو چھوٹا کر دیا گیا ۔ لاہور کو لوہے کے جنگلوں سے دیوار برلن کی طرح دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جنگلہ بس سروس سے لاہور کی اقتصادی ترقی کو ہمیشہ کے لیے محدود کر دیا گیا۔‘‘
ساری بات احساس کی ہوتی ہے خود پسندی‘ تنگ نظری او ر مفاد پرستی کے سبب‘ دل اگر پتھر نہ ہو جائیں تو ناکامی بھی سازگار ہوتی ہے۔ اصلاح اور کامیابی کا راستہ کھول سکتی ہے۔
احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے
کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی


 لاپتا بچوں کے حوالے سے خوف کی جو فضا قائم ہوچکی ہے، اس نے والدین کو سب سے زیادہ ہراساں کررکھا ہے جبکہ افواہ ساز فیکٹریوں کا کاروبار بھی عروج پر ہے۔ لوگ اپنے مخالفین کو بھی اغوا کار قرار دے کر تشدد کر نے لگے ہیں۔ ذہنی معذوروں اور مزدوروں پر تشدد تو ہوا ہی ہے، لیکن صورت حال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ خود روتے ہوئے بچے کے والد اور ماموں بھی مشتعل افراد کے ظلم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اجنبی خاتون پر بھرے بازار میں تشدد کرتے ہوئے کپڑے تک پھاڑ دینے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کررہی ہیں۔
لاپتا بچوں کے حوالے سے خوف کی جو فضا قائم ہوچکی ہے، اس نے والدین کو سب سے زیادہ ہراساں کررکھا ہے جبکہ افواہ ساز فیکٹریوں کا کاروبار بھی عروج پر ہے۔ لوگ اپنے مخالفین کو بھی اغوا کار قرار دے کر تشدد کر نے لگے ہیں۔ ذہنی معذوروں اور مزدوروں پر تشدد تو ہوا ہی ہے، لیکن صورت حال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ خود روتے ہوئے بچے کے والد اور ماموں بھی مشتعل افراد کے ظلم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اجنبی خاتون پر بھرے بازار میں تشدد کرتے ہوئے کپڑے تک پھاڑ دینے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کررہی ہیں۔

 انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے کہ یہ اس کا بلٹ ان پروگرام ہے، جس سے کسی صورت پیچھا نہیں چھڑایا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، افسوس اور رحم کے جذبات ہر کسی کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ مجبور اور بے بس چاہے اپنا ہو یا غیر، مدد کرنے کی امنگ ہر انسان کے دل میں اُٹھتی ہے۔گرتے ہوؤں کو تھام لینا بھی اسی فطرت کا اظہار ہے۔ اور پھر اگر معاملہ بچوں کا ہو تو ان ننھے فرشتوں کے لیے تو ہر کسی کا دل پسیج جاتا ہے۔ ان پھولوں کے لیے ہر شخص اپنے اندر رحم اور شفقت کے جذبات محسوس کرتا ہے۔
انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے کہ یہ اس کا بلٹ ان پروگرام ہے، جس سے کسی صورت پیچھا نہیں چھڑایا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، افسوس اور رحم کے جذبات ہر کسی کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ مجبور اور بے بس چاہے اپنا ہو یا غیر، مدد کرنے کی امنگ ہر انسان کے دل میں اُٹھتی ہے۔گرتے ہوؤں کو تھام لینا بھی اسی فطرت کا اظہار ہے۔ اور پھر اگر معاملہ بچوں کا ہو تو ان ننھے فرشتوں کے لیے تو ہر کسی کا دل پسیج جاتا ہے۔ ان پھولوں کے لیے ہر شخص اپنے اندر رحم اور شفقت کے جذبات محسوس کرتا ہے۔