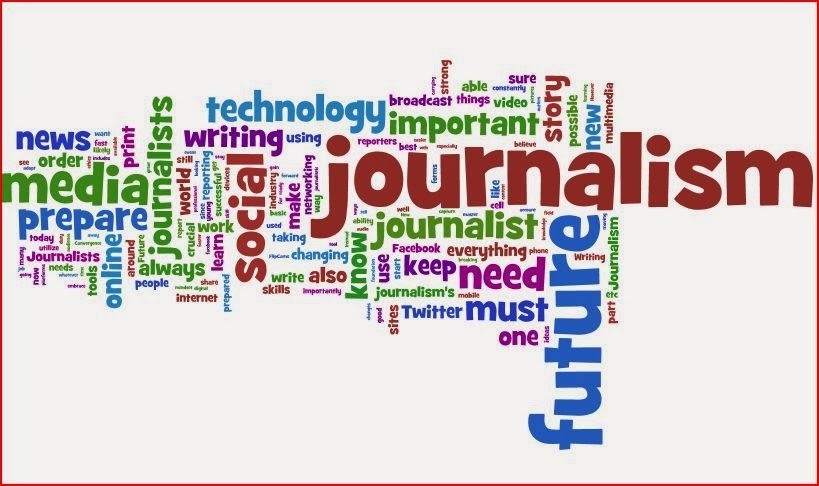پندرہ برس قبل جب کارجو (entrepreneur) مائیکل سٹاشولم نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا تو ان کے دوست نے انہیں سہانے مستقبل اور بے شمار کامیابیوں کے خواب دکھائے۔ سٹاشولم نے بھی اپنے دوست کی باتوں کا یقین کرلیا اور بہت برجوش ہوگئے جیسے کہ ان کی باتوں سے مستقبل واقعی بہت حسین ہونے جارہا ہو۔ آخر مثبت سوچ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ نہیں؟
پندرہ برس قبل جب کارجو (entrepreneur) مائیکل سٹاشولم نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا تو ان کے دوست نے انہیں سہانے مستقبل اور بے شمار کامیابیوں کے خواب دکھائے۔ سٹاشولم نے بھی اپنے دوست کی باتوں کا یقین کرلیا اور بہت برجوش ہوگئے جیسے کہ ان کی باتوں سے مستقبل واقعی بہت حسین ہونے جارہا ہو۔ آخر مثبت سوچ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ نہیں؟
”مثبت سوچ بہت سارے کارجووں کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے.“
یہ کہنا ہے سٹاشولم کا جو کوپن ہیگن میں مقیم ہیں۔ انہوں نے جہازرانی کی کمپنی Mearsk سے آغاز کیا تھا اور پھر کئی بڑی کمپنیوں کے مشیر کے طور پر کام کیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ:
”اگر آپ کی سوچ مثبت نہیں ہے تو آپ کبھی کاروبار شروع ہی نہیں کرسکتے۔“
تاہم جب ان کے کاروبار پر برا وقت آیا تو انہیں ایک اور سبق سیکھنے کو ملا۔ وہ یہ کہ مثبت سوچ کے کچھ تاریک پہلو بھی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ:
”محض مثبت سوچ اور بےفکرا پن کافی نہیں ہیں۔ آدمی کو تھوڑا حقیقت پسند بھی ہونا چاہیے“۔
1936 میں نپولین ہل کی کتاب ”سوچیے اور امیر ہوجائیے“ کی اشاعت کے بعد سے مثبت سوچ کو کاروباری لوگوں کے ہاں ایک رہنما اصول کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ دو عشروں بعد نورمنٹ ونسنٹ کی ”مثبت سوچ کی طاقت“ شائع ہوئی جو اتنی مقبول ہوئی کہ دنیا بھر میں اس کے دو کروڑ سے زائد نسخے فروخت ہوئے۔ جبکہ حال ہی میں رہونڈا بائرن نے اپنی کتاب اور ڈاکیومنیڑی ”راز“ کے ذریعے مثبت سوچ کے ذریعے کامیابی کے پیغام سے کاروباری لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی مسحور کیا ہے۔
مثبت سوچ کے متعلق ان کتابوں کا پیغام یہ ہے کہ منفی سوچیں کامیابی کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ مگر تازہ تحقیقات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مثبت سوچ کے کچھ محدودات بلکہ اپنے نقصانات بھی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مثبت سوچ آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بن رہی ہو!
”مثبت سوچ پر نظرثانی“ نامی کتاب کی مصنفہ گبیریئلے اوٹنگن جو نیویارک یونیورسٹی میں نفسیات کی پروفیسر ہیں، کہتی ہیں کہ جب انہوں نے مثبت سوچ پر تحقیق شروع کی تو انہیں معلوم ہوا کہ جب لوگ مستقبل کے متعلق خوش کن تخیلات جیسے کہ اپنی پسندیدہ نوکری یا دولت کے حصول میں مگن ہوتے ہیں تو ان کی توانائی (جس کا پیمانہ انہوں نے فشار خون کو بنایا) کم ہوجاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ:
”مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے حصول کے لیے درکار توانائی نہیں بڑھاتے“۔
ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مستقبل کے متعلق خوش کن تخیلات پالنے والے لوگ اکثر اپنے اہداف کے واقعی حصول کے لیے درکار کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر انہیں اپنی تحقیق کے دوران پتا چلا کہ دو سال کے عرصے کے بعد یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے ایسے طلبہ جنہوں نے اپنے مستقبل کے متعلق خوش کن تصورات کیے تھے کی آمدنی اور ان کو ہونے والی ملازمت کی پیشکشیں ایسے طلبہ کی نسبت کم تھیں جو اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ پریشان اور شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ مزید تحقیق پر معلوم ہوا کہ دراصل ان طلبہ نے نوکری کے لیے درخواستیں ہی کم دی تھیں۔ پروفیسر اوٹنگن کہتی ہیں کہ ایسے لوگ مستقبل کے متعلق خوش کن تصورات کرتے ہیں اور انہیں یوں لگنا شروع ہوجاتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ حاصل کرچکے ہیں۔ یوں ان کے اندر کچھ کرنے کے لیے درکار تحریک ختم ہوجاتی ہے۔
نمیتا شاہ جو لندن میں کیریئر سائیکالوجسٹس نامی ایک گروپ کی ڈائریکٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اکثر ایسے لوگ آتے ہیں جو اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر پا رہے۔ پھر وہ اس احساسِ جرم میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ ان کی سوچ منفی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اپنی خواہشات پوری نہ کرپانے کی ایک وجہ ان کی یہ منفی سوچیں بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ:
”مستقبل کے متعلق خوش کن خیالات بھی خوراک میں فوری نوعیت کے ٹوٹکوں کے استعمال جیسے ہیں۔ ان سے تھوڑی دیر کے لیے تو جوش پیدا ہوتا ہے لیکن آگے چل کر یہ تخیلات لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔“
تو کیا ہمیں زیادہ پریشان ہونا اور بدتر مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے؟ یہ بہت مشکل ہے۔
”امیدپرستی کی طرف غیر متوازن میلان“ کی مصنفہ اور لندن میں انسانی ذہن پر جذبات کا مطالعہ کرنے والے Affective Brain Lab نامی گروپ کی ڈائریکٹر طالی شیروت کے مطابق امید پرستی انسانی نفسیات میں پیوست ہے۔ جذبات پر ناخوشگوار واقعات کے مطالعے کے دوران ان پر منکشف ہوا کہ انسان اپنی ذہنی ساخت کے لحاظ سے ہی مثبت سوچنے پر مجبو رہے۔ اپنی تحقیق کے آغاز میں انہوں نے لوگوں سے تعلق ختم ہوجانے یا ملازمت چلی جانے جیسے ناخوشگوار اور منفی منظرناموں کے بارے میں سوچنے کو کہا تو انہیں یہ دلچسپ بات معلوم ہوئی کہ لوگ خودکارانہ انداز میں منفی منظرناموں کو مثبت منظر ناموں سے بدل دیتے ہیں۔ مثلاً لوگوں نے ایسے منظر نامے تخلیق کیے کہ ان کا کسی تعلق ٹوٹا تو انہیں اس سے بہتر رفیق مل گیا۔ طالی شیروت کہتی ہیں کہ اس طرح ان کے اصل تجربے کا تو ستیاناس ہوگیا لیکن انہیں یہ احساس ہوا کہ لوگ امید پرستی کی طرف غیر متوازن جھکاؤ رکھتے ہیں۔
”لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل ماضی سے بہتر ہوگا“۔
امید پرستی کی طرف یہ غیر متوازن جھکاؤ جو ان کی تحقیق کے مطابق ہر ملک اور کلچر کی تقریباً اسی فیصد آبادی میں پایا جاتا ہے، شیروت کے خیال میں انسانوں کو تحریک دلانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تحقیقات یہ بھی بتاتی ہیں کہ امید پرست لمبی زندگی پاتے ہیں اور زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ ان کے مطابق مثبت خیالات خود کو درست ثابت کرنے کا موجب بھی بن سکتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک جیئیں گے وہ صحت بخش خوراک استعمال کرنا اور ورزش کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امید پرستی انسانوں کو (بہتر مستقبل کی امید میں) مشکل حالات سہنے میں بھی مدد دیتی ہے۔
لیکن یہی امید پرستی انسانوں کو خطرات کو نظرانداز کرنے پر بھی مائل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر امید پرستی کی وجہ سے آپ کو کسی منصوبے پر اٹھنے والی لاگت اور لگنے والے وقت کا صحیح اندازہ لگانے میں ناکام ہوسکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حد سے بڑھی ہوئی امید پرستی خطرناک ہے اور یہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتی ہے۔
لیکن اگر ہم فطری طور پر مثبت سوچنے کے ہی عادی ہیں تو پھر آنکھوں پر پڑے امید پرستی کے پردے ہٹانے کے لیے کچھ محنت درکار ہوگی۔
اپنی دو عشروں پر محیط تحقیق کی روشنی میں پروفیسر اونٹنگن نے ایک کلیہ وضع کیا ہے جو خواہش، نتیجے، رکاوٹ اور منصوبے کے اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ ان کی ویب سائٹ اور سمارٹ فون ایپ کی صورت میں دستیاب ہے اور اس میں ایسی مشقیں ہیں جو مثبت سوچ کے ساتھ ساتھ مشکلات اور ممکنہ ناخوشگوار پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا کر آپ کو اپنے قلیل اور طویل مدتی اہداف کے حصول کے لیے کارآمد لائحہ عمل مرتب کرنے میں مدد دیتی ہیں۔
مثال کے طور پر اگر آپ ایک کمپنی شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ تو نہ تو پیسے مانگ سکتے ہیں اور نہ ہی بہت دیر تک کام کرسکتے ہیں تو پھر آپ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کرسکتے ہیں، جیسے کہ اپنی ٹیم میں سیلزمین کو شامل کرسکتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ اوقات میں ہی کام کرسکتے ہیں۔ یا پھر یہ ہوسکتا ہے کہ ان مشکلات کا اندازہ کرنے کے بعد آپ کام شروع کرکے نقصان اٹھانے سے پہلے ہی فیصلہ کرلیں کہ آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔
پروفیسر اونٹینگن کہتی ہیں کہ اس طرح آپ اس طرح کے اہداف کو بغیر کسی افسوس کے ترک کر سکتے ہیں کہ میں نے اس پر غور کیا ہے لیکن یہ فی الحال میری زندگی میں فٹ نہیں بیٹھتا۔
جب سٹاشولم نے چند سال قبل اپنی ماحول دوست پنسلیں بنانے والی کمپنی شروع کی تو انہوں نے اپنی پچھلی ناکامیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے تمام معاہدات لکھ کر بدترین حالات کے لیے منصوبہ بندی کی۔ اب ان کی کمپنی ایک ماہ میں ساٹھ مختلف ملکوں میں کوئی ساڑھے چار لاکھ پنسلیں بیچتی ہے۔ اتنی کامیابی پر خود سٹاشولم بھی حیران ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ:
 ”ہر کوئی کاروبار میں مثبت سوچ اپنانے کی بات کرتا ہے لیکن مثبت سوچ کا الٹ منفی سوچ نہیں ہے۔ لیکن آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ وہ کیا حاصل کرسکتا ہے اور کیا نہیں۔“
”ہر کوئی کاروبار میں مثبت سوچ اپنانے کی بات کرتا ہے لیکن مثبت سوچ کا الٹ منفی سوچ نہیں ہے۔ لیکن آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ وہ کیا حاصل کرسکتا ہے اور کیا نہیں۔“
(یہ مضمون Renuka Rayasam کے مضمون Positive Thinking Can Make You Too Lazy to Meet Your Goals کا ترجمہ ہے جو بی بی سی ڈاٹ کام پر شائع ہوا. عاطف حسین صاحب نے اسے اردو کے قالب میں ڈھال کر دلیل کو فراہم کیا ہے.)


 مولانا الیاس گھمن سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا مضمون یکطرفہ الزامات اور بہتان تراشی کی طویل داستان معلوم ہوتا ہے۔ لکھنے والا وہ جو ان میں سے کسی واقعے کا بھی عینی شاہد نہ تھا۔ ایک خاتون کے حوالے سے ایسے ایسے الزامات اور واقعات بے دھڑک لکھے اور شائع ہوئے کہ کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوتا تھا۔ کسی عام آدمی کے بارے میں بھی ایسا سوچنا محال ہے کجا یہ کہ منبر و محراب کے وارث کے بارے میں ایسے ہوش ربا انکشاف کیے جائیں۔ مولانا الیاس گھمن سے ہزار اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر یوں کردار شکنی اور کیچڑ اچھالنے کا کلچر ہرگز قابل قبول نہیں۔
مولانا الیاس گھمن سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا مضمون یکطرفہ الزامات اور بہتان تراشی کی طویل داستان معلوم ہوتا ہے۔ لکھنے والا وہ جو ان میں سے کسی واقعے کا بھی عینی شاہد نہ تھا۔ ایک خاتون کے حوالے سے ایسے ایسے الزامات اور واقعات بے دھڑک لکھے اور شائع ہوئے کہ کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوتا تھا۔ کسی عام آدمی کے بارے میں بھی ایسا سوچنا محال ہے کجا یہ کہ منبر و محراب کے وارث کے بارے میں ایسے ہوش ربا انکشاف کیے جائیں۔ مولانا الیاس گھمن سے ہزار اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر یوں کردار شکنی اور کیچڑ اچھالنے کا کلچر ہرگز قابل قبول نہیں۔
 کہانی ہو کہ افسانہ، مضمون ہو یا خاکہ، تنقید سے کچھ بھی مبرا نہیں مگر تنقید بےسروپا لفظوں کو صفحے پر کھینچنے کا نام نہیں ہے۔ نقاد کے کندھوں پر معیار، اسلوب اور نکتہ آفرینی کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہر جملہ دلیل نہیں ہوتا اور ہر دعوی سچ نہیں بنتا جب تک کہ منطق اور حوالوں کی بھٹی سے کندن ہو کرنہ نکلے۔
کہانی ہو کہ افسانہ، مضمون ہو یا خاکہ، تنقید سے کچھ بھی مبرا نہیں مگر تنقید بےسروپا لفظوں کو صفحے پر کھینچنے کا نام نہیں ہے۔ نقاد کے کندھوں پر معیار، اسلوب اور نکتہ آفرینی کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہر جملہ دلیل نہیں ہوتا اور ہر دعوی سچ نہیں بنتا جب تک کہ منطق اور حوالوں کی بھٹی سے کندن ہو کرنہ نکلے۔