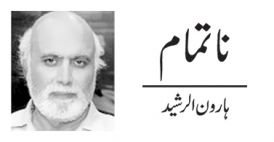اس وقت پاکستان کا صحافتی منظرنامہ دو واقعات سے گونج رہا ہے۔ ابھی سیرل المیڈا کی خبر پر اٹھنے والا شور وغوغا مدھم نہیں ہوا تھا کہ عروس البلاد کراچی میں ایک خاتون اینکر کو رینجرز کے ایک اہل کار نے ’کارِ سرکار میں مداخلت پر‘ چٹاخ سے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ دونوں واقعات کا بظاہر ایک دوسرے سے دور کا بھی تعلق بھی نہیں نظر نہیں آتا لیکن اگر احتیاط سے دیکھا جائے تو دونوں واقعات کے ڈانڈے ایک ہی جگہ سے جا کر ملتے ہیں۔
اس وقت پاکستان کا صحافتی منظرنامہ دو واقعات سے گونج رہا ہے۔ ابھی سیرل المیڈا کی خبر پر اٹھنے والا شور وغوغا مدھم نہیں ہوا تھا کہ عروس البلاد کراچی میں ایک خاتون اینکر کو رینجرز کے ایک اہل کار نے ’کارِ سرکار میں مداخلت پر‘ چٹاخ سے ایک تھپڑ جڑ دیا۔ دونوں واقعات کا بظاہر ایک دوسرے سے دور کا بھی تعلق بھی نہیں نظر نہیں آتا لیکن اگر احتیاط سے دیکھا جائے تو دونوں واقعات کے ڈانڈے ایک ہی جگہ سے جا کر ملتے ہیں۔
کوئی دور تھا کہ صحافت میں صرف اہل الرائے اور نظریاتی لوگ ہی آیا کرتے تھے، کیوں کہ صحافت میں تنخواہیں بہت کم ہوا کرتی تھیں اور وہ بھی کبھی کبھار ہی ملتی تھیں۔ جب ہم جیسے جونیئرز اپنے سینیئرز سے اس حوالے سے شکوہ کناں ہوتے تو جواب ملتا کہ ’جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں‘؟ صحافیوں کو معاشرے میں بیک وقت رحم اور خوف کی نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ ہمیں بتایا جاتا کہ صحافت واحد شعبہ ہے جس میں پچاسی فی صد سے زائد لوگوں کو تنخواہ تو ملتی ہی نہیں تھی۔ اس حوالے سے ضلعی اور علاقائی نامہ نگاروں کا حوالہ دیا جاتا جو ہر گلی محلے میں اعزازی طور پر کام کرتے اور کسی عوضانے یا تنخواہ کے طلب گار نہ ہوتے۔ بڑے بڑے اخبارات بھی ان کو فی سطر کے لحاظ سے ادائیگی کرتے جو ان کے قلم کی سیاہی کا خرچ بھی پورا نہ کرپاتی۔
پھر گذشتہ صدی کی اسی کی دہائی میں لاہور میں ایک رحجان ساز تبدیلی آئی جب کچھ صحافیوں نے ایڑیاں اٹھا کر میڈیامیں شامل ہونے کی کوشش کی اور علاقائی نامہ نگاروں کو کہہ دیا گیا کہ ’’اپنا کھا آنا، اور ہمارے لیے لیتے آنا‘‘یعنی ان اخبارات نے پورے ملک کے ہر گلی محلے میں پھیلے اپنے نمائندگان اور نامہ نگاروں کے ذمے لگایا کہ وہ ہر محلے سے انہیں اس قدر رقم بھیجیں ، بھلے وہ اخبار اس قابل ہے یا نہیں کہ اس کو اشتہار دیا جا سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے پورے معاشرے میں بلیک میلروں کے سیلاب کا ایک ریلا کھول دیا۔ کبھی تھانے بکتے ہوں گے یا پھر ائیرپورٹس پر امیگریشن کے کاؤنٹر بکتے ہوں گے اب شہروں کے بیورو بھی بکنے لگے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخبارات نے پولیس کے متوازی ایک حکومت قائم کر لی جو ہر سرکاری ادارے کی بدعنوانی کے یا تو حصہ دار تھے یا پھر پشتی بان۔ اور جہاں پر وہ یہ نہ ہوتے تو اس کی خبر چھپ جاتی۔
ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا رشتہ گیا تو ہماری ہونے والی زوجہ محترمہ کی نانی (مرحومہ) نے دریافت کیا کہ ’لڑکا کرتا کیا ہے‘‘ تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اخبار نویس ہے۔ اس پر انہوں نے بڑے تحمل سے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کام کیا کرتا ہے؟ ہماری بیٹی کو کہاں سے کھلائے گا؟ ہم انہیں شادی کے دس سال بعد تک نہ سمجھا پائے کہ اس شعبے میں بھی تنخواہ دینے کا رواج ہو گیا ہوا ہے۔ اس صدی کی ابتدا تک اگرچہ حالات بہت خراب ہو چکے تھے لیکن بلیک میلنگ کے لیے آنے والے صحافی کا قلم جیب میں ہی چھپا ہوا تھا اور خال ہی باہر آتا، جب اسے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت ہوتی۔
لیکن نجی ٹی وی کی آمد نے تو بیچ چوراہے بھانڈہ پھوڑ دیا۔ اب تو صحافی (خصوصاً علاقائی) ہاتھ میں مائیک ایسے لہراتا ہے جیسے مولا جٹ گنڈاسہ لہرایا کرتا تھا۔ لاہور کے ایک ٹی وی نے اپنے ایک نامہ نگار کو ایک جعلی ڈی ایس این جی محض اس لیے بنوا کر دی ہے کہ وہ اپنے علاقے کو کنٹرول کر سکے۔ یار دوستوں کو معلوم ہے کہ اس وین کے اوپر جڑی ڈش کا مصنوعی سیارے سے دور کا بھی واسطہ نہیں لیکن اس سے کسی کو کیا لینا دینا، ساہی وال کی نواحی اوکاڑہ چھاؤنی کے علاقے کا یہ شاہکار رپورٹر مختلف صنعت کاروں اور تاجروں کے گھروں کے باہر اپنی یہ ڈی ایس این جی کار کھڑی کرتا ہے اور انہیں دھمکی دیتا ہے کہ وہ ان کے کاروبار کی بد اعمالیوں اور سیاہ کاریوں پر ’براہِ راست‘ نشریات شروع کرنے لگا ہے۔ اور من کی مراد پا کر واپس آتا ہے۔ ایک دفعہ جب ایک کثیر القومی ادارے کے مقامی دفتر نے ان کے مطالبات پورے کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے خبر چلوا دی کہ اس ادارے کے پاس لاکھوں ایسی سمیں موجود ہیں جو طالبان کو فراہم کی جاتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کی دوڑ میں شامل میڈیا نے بغیر تحقیق کے اس پر پروگرامات بھی کر ڈالے۔ وہ تو بعد میں جب اصل حقیقت آشکار ہوئی تو مقامی پولیس اور ملک کے سب سے بڑے ’خفیہ ادارے ‘ نے مل ملا کر معاملہ دبا دیا۔ کیوں کہ اس میں کچھ ’پردہ نشینوں‘ کے بھی نام آتے تھے۔
لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس معاشرے نے دو دہائیوں میں میڈیا متاثرین کی جو ایک نسل تیار کی ہے وہ اب پیسے کے زور پر میڈیا مالکان کی صف میں شامل ہو رہی ہے۔ چوں کہ ان کو بلیک میل کر کے ان کی راتوں کی نیند حرام کرنے والا صحافی دراصل ایک رپورٹر ہی ہوا کرتا تھا، اس لیے صحافت اور صحافی (رپورٹر) سے نفرت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس لیے نئے میڈیا مالکان کا بس نہیں چلتا کہ وہ صحافیوں کو ذلیل کر کے اپنی عزتِ نفس مجروح کرنے کا انتقام ان سے لیں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ایک اجلاس کی اندرونی کہانی کی خبر ایک ایسے صاحب نے دی جن کا رپورٹنگ کا ایک دن کا بھی تجربہ نہیں۔ ایک پیدائشی رپورٹر کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح کی سمری موصوف کے ہاتھ لگی ہے، اس طرح کی بہت سی دستاویزات روزانہ کی بنیاد پر ایک رپورٹر کے ہاتھ لگتی ہیں، لیکن اس کے اندر کا سنسر بورڈ فوراً اس طرح کی خبروں کو مسترد کر دیتا ہے۔ چوں کہ موصوف کے فرشتوں نے تمام عمر ایسا کام نہیں کیا تھا بلکہ انہیں تو سکھایا ہی چھپی ہوئی خبر پر تبصرہ کرنا تھا، اس لیے موصوف نے اپنی خبر میں وہ اعلیٰ قسم کی بونگیاں ماری ہیں کہ صحافت سر پیٹتے ننگے سر بازار میں نکل آئی ہے۔
میڈیا مالکان نے دوسرا انتقام صحافت سے یہ لیا ہے کہ صحافی کون ہے؟ اور اس کی اوقات کیا ہے؟ صحافی کو اس کی اوقات یاد دلوانے کے لیے اسے کیمرے کے سامنے سے اٹھا کر کیمرے کے پیچھے بٹھا دیا گیا اور کیمرے کے سامنے ایک حشرسامان بیگم جان براجمان ہو گئی ہیں۔ محرومی اور ڈپریشن کا شکار خبر سننے کے لیے رکے یا نہ رکے، اس بیگم جان کو دیکھنے کے لیے ضرور رکتی ہے۔ جس خاتون کو ’مدعہ ای اے بھائی‘ کہہ کر پورے رپورٹنگ روم میں منہ نہیں لگایا کرتا تھا، اب وہ ملک کی ٹاپ رینکنگ اینکر ہوتی ہے۔ یہ وہ انتقام ہے جو ہر میڈیا مالک نے ہم جیسے صحافیوں سے لیا ہے۔ دوسری طرف ہر تعلیم فروش، سوتر فروش، سگریٹ فروش، کیبل فروش اور ضمیر فروش اب میڈیا مالکان کی صف میں گھس آیا ہے۔
اب کراچی میں تھپڑ کھانے والی خاتون کو اگر میڈیا پروڈکشن یا صحافت کے معیار کے طور پر دیکھیں تو کسی طور بھی پرائم ٹائم کیا انہیں سرے سے ہی سکرین پر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سہاگن وہ جو پیا من بھائے۔ چوں کہ وہ اس چینل کے مالک صاحب کو پسند ہیں ، اس لیے ’ضروری ہیں‘۔ اس کے بعد انہوں نے جو حرکت فرمائی وہ سبحان اللہ۔ ہمیں پہلے دن بتایا گیا تھا کہ ادارے کا نکتہ نظر اس کے سربراہ سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر پولیس کا آئی جی نہ ملے تو کم ازکم ڈی آئی جی سے کم بات نہ کرنا۔ لیکن موصوفہ نے تو ایک سپاہی کو ہی بتانے کی کوشش کی کہ اس کے گھر میں ماں بہن ہوتی ہے کہ نہیں۔
بہادر کمانڈو جنرل پرویز مشرف صاحب کی اعلیٰ پالیسیوں کے باعث ان کے ادارے کے بارے میں لوگوں کی پسندیدگی اس انتہا کو پہنچی تھی کہ ادارے کو یہ بات نوٹی فائی کرنا پڑی تھی کہ ادارے کا کوئی افسر یا ملازم یونیفارم میں عوامی جگہوں پر نہ جائے۔ یہ دور صحافت میں آیا ہی چاہتا ہے کہ کسی بھی جگہ صحافی کا تعارف کروانے پر لوگ باقی کام چھوڑ کر آپ کی ’آؤ بھگت‘ میں مصروف ہو جائیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ پیشے کے خانے میں استاد، لکھنا شروع کردیں کہ اب صحافی کا تعارف کروانا بھی ایک جرم سا لگنے لگا ہے۔
ان دونوں واقعات کے پس منظرمیں صحافتی پیشہ وراریت کی نہیں اخلاقی تربیت کی شدید کمی کارفرما نظر آتی ہے اور اس عمر میں ان کو یہ باتیں تو سکھائی نہیں جاسکتیں کیوں کہ یہ بنیادی باتیں انہیں ماں کی گود سے سیکھنا تھیں جہاں سے نکلے انہیں عرصہ بیت چکا ہے۔