مقدمہ “دور جدید کے مذہب گریز نظریات کی بحث اور ہمارے مذہبی طبقے کا جمود”
ہمارا مذہبی طبقہ جمود کا شکار ہے ، جی ہاں ہمارا مذہبی طبقہ جمود کا شکار ہے اور یہاں مذہبی طبقے سے مراد کسی خاص مسلک ، مکتب فکر ، گروہ یا جماعت سے نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی مذہبی طبقے سے ہے۔
یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جب ہم جمود کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد جدیدیت کی دعوت نہیں ہے اور نہ ہی تجدد پرستی کا اعلان ہے بلکہ جمود سے مراد دور جدید کے مذہب گریز نظریات کو سمجھ کر روایت کی روشنی میں ان کے سدباب کی طرف متوجہ کرنے کی ہے۔ ہمارا آج کا روایت پسند مذہبی طبقہ اس وجہ سے جمود کا شکار نہیں کہ وہ روایت سے جڑا ہوا ہے اور اپنی روایت کی بنیاد پر جمود کا شکار ہے بلکہ عجیب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ روایت سے کٹ چکا ہے اور اپنی حقیقی روایت سے ہٹ کر جس راستے پر چل رہا ہے اسے ہی حقیقی سمجھ کر جمود کا شکار ہے۔
جب آپ اپنے مذہبی طبقے کے سامنے مذہب گریز نظریات کی گفتگو پیش کرتے ہیں تو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ مایوسی صرف خالص روایت پسند گروہوں کی جانب سے ظاہر کردہ رویے پر ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ مایوسی ان طبقات کے رویے کو دیکھ کر بھی ہوتی ہے کہ جن کی تخلیق کا دعویٰ ہی یہ تھا کہ وہ روایتی مذہبی طبقے کی اصلاح کیلئے کھڑے ہوئے تھے ، مگر افسوس کہ جس دعوے کو لے کر وہ کھڑے ہوئے تھے اور جس امر کی مخالفت کا ڈنکا وہ بجانا چاہتے تھے خود اسی جمود کا اس سے زیادہ شدت کے ساتھ شکار ہوگئے۔
جب ہم مذہب گریز نظریات سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کا دائرہ کا ماضی کے سوفسطائیہ سے دور جدید کے ارتیابیوں تک پھیلا ہوا ہے. ان نظریات کی شکل پیرامڈ کی طرح ہے کہ جس کی بنیادیں تشکیک پر قائم ہیں. تشکیک بطور نظریہ بھی اور تشکیک بطور رویہ بھی ، تشکیک کی بنیاد پر قائم اس اہرام کے مختلف درجات ہیں. تشکیک ہمیں روایت گریزی کی طرف لے جاتی ہے. روایت گریزی سے مراد اس راہ کو کھوٹی کردینا اسلام کا وہ پیٹا پاٹا راستہ چھوڑ دینا اس الصراط سے ہٹا دینا کہ جسے منہج سلف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے.
اگر ہم تشکیک کے وائرس کو دیکھیں تو یہ روایت کے امیون سسٹم پر حملہ آور ہوتا ہے ، جدید مسلم دنیا میں تشکیک استشراقی فکر کی شکل میں وارد ہوئی، وہ استشراقی فکر کے جو چرچ تک محدود تھی. استعمار کی چھتر چھایہ میں ہمارے گڑھوں تک چلی آئی ، استشراقی فکر نے تشکیک کے کام کو ہی آسان کیا اور اس تشکیک کو علمی مواد فراہم کرکے ہماری تمام تر ثقافتی ، تاریخی ، علمی ، فکری اور اعتقادی مسانید تک پہنچا دیا ، اس استشراقی فکر کا اصل کام یہ تھا کہ ہم پر ہماری تاریخ ، ہماری سیاست ، ہماری فقہ ، ہمارا تصوف ، ہماری حدیث اور ہماری تفسیر سبھی کچھ مشکوک ہوجائے یہ وہ پہلا پھندا تھا کہ جس میں ہمیں جکڑا گیا۔
جیسا کہ اوپر عرض کی اس سب خرابے کی ابتداء تشکیکی رویہ تھا پھر اسی تشکیک نے استشراقی فکر سے علمی و فکری مواد حاصل کیا اور یہ استشراقی فکر استعمار کے کاندھوں پر سوار ہوکر ہم تک پہنچی ، غور کیجئے اور بار بار غور کیجئے تفکر کی آنکھیں کھولیے شعور کے در وا کریں. پھر سوچیے پھر سے سوچیے وہ تمام پردے کہ جو اپنی روایت سے دوری کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر پڑ چکے ہیں. انہیں اتار کر دیکھنے کی کوشش کریں ، جب ہماری روایت کی جڑیں صاف ہو رہی ہوتی ہیں تو دوسرے راستے سے مذب گریز نظریات ان کی جگہ لے رہے ہوتے ہیں. یعنی گلشن تو ہمارا اور اس کی گلشن کی زمین میں خار دوسروں کے اور پیر اس امت کے لہو لہان۔
آپ کے ہاتھ سے تصور خلافت نکلتا ہے تو سیکولر ازم قومی وطنیت کی شکل میں جمہوریت کے نام پر آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے ، جب آپ کے ہاتھ سے اسلامی علم الکلام نکلتا ہے تو جدید فلسفہ آپ کا گھر دیکھ لیتا ہے ، جب آپ کے ہاتھ سے تصوف نکلتا ہے تو باطنیت و رہبانیت آپ کے دروازے تک چلی آتی ہے. اور آپ کے بالا خانوں میں وحدت ادیان کی آوازیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں ، جب آپ کے ہاتھ سے اسلام کا تصور اخلاقیات نکلتا ہے تو ہیومنزم آپ کے کاندھوں پر سوار ہو جاتا ہے.
جب آپ کے ہاتھ سے حکمت و معرفت نکلتی ہے اور اطاعت گزاری کا جذبہ مفقود ہوتا چلا جاتا ہے تو لبرلزم آپ کو جکڑ لیتا ہے ، جب آپ صنفی تعلقات میں مذہبی اصولوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو فیمینزم آپ کے ذہن پر غالب ہو جاتا ہے ، جب توکل جاتا ہے تو مادیت کا غلبہ ہوتا ہے غرض یہ کہ آپ کے تمام تر پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں اور آخر کار یہ مذہب گریز نظریات و رویے سیڑھی در سیڑھی آپ کو الحاد کی چوٹی پر لا کھڑا کرتے ہیں۔
ایسا نہیں کہ اس تمام پراسیس کے درمیانی درجات نہیں ہیں جی ہاں اس کے درمیانی درجات بھی ہے اس سیڑھی کے وہ تمام اسٹیپس کہ جو مدرسے کی سیکولرائیزیشن سے ہوتے ہوئے کبھی اسلامی جمہوریت کی شکل میں تو کبھی اسلامی بینکاری کی شکل میں کبھی اسلامی فیمینزم کی شکل میں تو کبھی اسلامی نیشنلزم کی شکل میں غرض یہ کہ ہر وہ ازم کہ جس کا سکہ آج چلتا ہو اسلامی شکل میں آپ کے سامنے پیش کردیا جاتا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے درست بھی ہو لیکن تاریخ کے اوراق پر جب چند باب پلٹتے ہیں تو وہی معصومانہ تسامحات بڑے بڑے عفریتوں کی شکل میں نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو گفتگو ہو رہی تھی روایتی مذہبی طبقات کے جمود کے حوالے سے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک جگہ بحث چل رہی تھی وہاں پر عرض کی کہ ہمیں ان مذہب گریز نظریات کا روایت کی روشنی میں جواب دینا ہوگا وگرنہ یہ آخری میدان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. مگر افسوس کے سامنے سے اسی جمود کا اظہار ہوا ، ایک انتہائی قابل افسوس امر یہ ہے کہ ہر ہر مذہبی گروہ ، جماعت یا ادارہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ پورے کا پورا دین در حقیقت انہی کو سمجھ آیا ہے اور دین کے جس شعبے میں وہ محنت کررہے ہیں. دین تو صرف اسی سے زندہ ہوگا ، گو کسی درجے میں یہ غلو مطلوب بھی ہے کہ اس کے بغیر وہ غیر مشروط اطاعت اور بقول ابن خلدون عصبیت (مثبت معنی میں) حاصل نہیں ہوتی کہ جو تحریکوں ، جماعتوں ، گروہوں اور اداروں کو چلاتی ہے مگر یہ سوچ لینا کہ
ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار اس سے ہے
ہر سر یہی سمجھتا ہے دستار اس سے ہے
جی ہاں یہ سوچ اور یہ رویہ زہر قاتل ہے. جب ہم اپنی گفتگو میں مذہبی طبقات کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ جناب من ہمیں اپنی علمی و فکری روایت سے جڑے رہنا ہے. لیکن دور جدید کے مذہب گریز نظریات کے خلاف دلائل کا انداز کچھ الگ ہوگا تو ان کی جانب سے یہ رویہ سامنے آتا کہ ان کے حضرت ان کے مفکر ان کے لیڈر جو کچھ بھی فرما گئے وہ حرف آخر ہے. اور اس پر ایک لفظ تو کجا ایک حرف بلکہ کسی اضافت کی بھی گنجائش موجود نہیں اور جب انہیں یہ سمجھایا جائے کہ جناب فلاں مفکر کا کام ان کے دور کے اعتبار سے تو بہت شاندار تھا .
لیکن آج وہ غیر معتلق ہو چکا ہے آج وہ تمام دلائل کارگر نہیں ہیں اور ہمیں وہی گفتگو یاد رہے کہ وہی گفتگو آج کی زبان میں کرنی ہے تو انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی اور افسوس کہ یہ وہ مذہبی طبقات ہیں کہ جن کی تمام تر دعوت خود روایتی طبقات پر تنقید سے شروع ہوئی تھی۔ہماری گفتگو تجدد کی دعوت نہیں بلکہ روایت کا احیاء ہے ہم امت کو اس روایت سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ جو محمد عربی ﷺ کے صدقے میں ہمیں ملی وہ روایت کہ صحابہ رض اس کی اعلیٰ ترین عملی مثال تھے وہ روایت کہ ہمارے سلف جس کے امین تھے وہ روایت کہ جسے فقہاء و محدثین نے جلا بخشی وہ روایت کہ جو متکلمین سے ہمیں ملی وہ روایت کہ جو صوفیاء نے ہم تک پہنچائی ہم امت کو اسی روایت سے جوڑ دینے کے داعی ہیں۔
یاد رہے کہ دور جدید کے مذہب گریز نظریات کا ابطال اسی روایت کی روشنی میں ہوگا کہ جو ہماری روایت ہے ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ حال کے فتنے کو جاننا اور اس کے جوابات اپنی قدیم روایت کی روشنی میں آج کی زبان میں پیش کرنا۔
پروفیر حسن عسکری مرحوم اور ان کی جدیدیت
فکر و فن کے میدان میں پروفیسر حسن عسکری مرحوم ایک بڑا نام ہیں علم و ادب کے دائرے میں ان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، پروفیسر صاحب ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے نا صرف فکر و فلسفے اور علم و ادب کے میدان ایک بڑا کام کیا بلکہ وہ اس دائرے کے آدمی ہوتے ہوئے مذہب بیزار نہیں تھے بلکہ ان کا شمار مذہب پسندوں میں کیا جاتا ہے۔
پروفیسر صاحب اور ان کی معروف کتاب جدیدت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کی ضرورت اسلیے پیش آئی کی ابھی کچھ ہی دن ہوئے صدر وفاق مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس کتاب کو کچھ اور کتب کے ساتھ مدارس کے طلباء کیلئے تجویز فرمایا ہے اس تجویز کے ساتھ ہی اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کا ایک بازار گرم ہوگیا، بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کیلئے بہت سے لوگ اپنے اپنے دائروں سے نکل کر اس کتاب کو لے کر محاضرات ، سیمینارز اور تجزیوں کی محافل سجانے لگے یہ دیکھے بغیر کہ جس بات کا ڈول ڈالا جا رہا ہے اس کی عملی صورت کیا ہوگی اور وہ عملی صورت کس حد تک مفید ثابت ہوگی۔
یہ بات تو انتہائی خوش آئند ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ان موضوعات کو چھیڑا جا رہا ہے کہ جو دور جدید میں مذہب کے مقدمے کو لڑنے کیلئے انتہائی ضروری ہیں کم سے کم درجے میں ان عنوانات پر تخصصات کا ایک سلسلہ تو شروع ہوا چاہتا ہے اس سے پہلے تو ہم کالم نگاری ، صحافت ، انگریزی ، یوٹیوب اور بھانت بھانت کے جھمیلوں میں اپنا اور اپنے طالب علموں کا انتہائی قیمتی وقت گنوا چکے ہیں یہاں تک کہ ہمارا ایک انتہائی با صلاحیت طبقہ مدرسہ ڈسکورسز جیسے جھانسوں کا شکار ہو کر خود روایت سے تجدد کی طرف کوچ فرما چکا. گو کہ بڑی دیر کے بعد ہم نے یہ سلسلہ شروع تو کیا ہے لیکن اس میں کیا کچھ مسائل ہیں اس حوالے سے چند ایک تحفظات پیش کرنا انتہائی ضروری معلوم ہوتے ہیں۔
جدیدیت بطور کتاب
جدیدیت کو ایک مستقل کتاب قرار دینا ممکن نہیں گوکہ اس کتاب کی عام شہرت کی وجہ سے یہ بات شاید درست معلوم نہ ہو لیکن بہ نظر غائر تجزیہ کرنے کے بعد یہی رائے درست معلوم ہوتی ہے۔ جدیدت کو زیادہ سے زیادہ ہم ایک طویل مضمون قرار دے سکتے ہیں کہ جس میں مغرب کی فکری تاریخ کا ایک اجمالی خاکہ بیان کیا گیا ہے اسی کتاب کے دوسرے حصے میں فلسفہ مغرب کے کچھ عنوانات بیان ہوئے ہیں کہ جو صرف اشاروں کی شکل میں ہیں ، یہ بات انتہائی توجہ طلب ہے کہ کیا یہ کتاب بطور درسی کتاب کسی بھی درجے میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔
کتاب کا پہلا حصہ فلسفہ مغرب کی اجمالی تاریخ پر مبنی ہے کہ جو حوالہ جات کے بغیر ہے اسے صرف ایک شخصیت کی رائے یا حاصل مطالعہ کے طور پر لیا جا سکتا ہے، مزید اس حوالے سے گفتگو اتنی آگے جا چکی ہے کہ آج اس اجمالی تاریخ کو تفصیل سے سمجھے بغیر جدیدیت کے عنوان کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے.
کتاب کا دوسرا حصہ مغرب کے کچھ معروف فلسفوں کی بابت چند اشاروں پر مشتمل ہے. جن کو ایک عام طالب علم کیلیے سمجھنا انتہائی مشکل ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کو بطور درسی کتاب پڑھایا جائے گا تو اشکالات دور ہونے کے بجائے مزید پیدا ہو جائیں گے۔
کیا جدیدیت کو بطور نصابی کتاب پڑھایا جا سکتا ہے ؟
بطور طالب علم فلسفہ مغرب کے مطالعے اور بطور مدرس لامذہبی نظریات کی تاریخ و فلسفے کو پڑھانے کے بعد ایک زمانے میں یہ ارادہ ہو کہ اردو میں ایک ایسی کتاب پڑھائی جائے کہ جو فلسفہ مغرب کے مضر اثرات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کا توڑ پیش کر سکے ، اردو زبان میں متعدد کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے اس حوالے سے کوئی مواد تیار ہی نہیں کیا یہ بات انتہائی حیران کن بھی ہے اور افسوس ناک بھی ہے کہ ہم نے مغربی فکر کی خرابیوں کا نہ تو درست ادراک کیا اور نہ ہی ان کا اثر توڑنے کیلئے کوئی خاص علمی مواد تیار کیا۔
اب اگر جدیدیت پر غور کیا جائے تو یہ بات انتہائی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھانے کیلیے ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے کہ جو خود فلسفہ مغرب پر عبور رکھتے ہوں یعنی اس کتاب کو پڑھانے والا ایک جانب تو مغربی مصادر کا براہ راست درک رکھتا ہو اور دوسری جانب اس کے علمی رد سے بخوبی واقف بھی ہو ، یہ تو ممکن ہے کہ انفرادی سطح پر ہماری روایتی درسگاہوں میں ایسی علمی شخصیات موجود ہوں لیکن بحیثیت مجموعی ہمارے پاس ایسے اساتذہ موجود نہیں کہ جدیدیت کو بطور نصابی کتاب تجویز کیا جا سکے۔
دوسری جانب ہمارے عصری تعلیمی اداروں میں فلسفہ مغرب کے حوالے سے بہت سی معتبر شخصیات ضرور موجود ہیں لیکن وہ مذہب کی کلامی روایت اور روایتی فکر سے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں ، ایسی شخصیات سے ان کتب کا پڑھوانا درحقیقت جدیدیت سے تجدد کی طرف لے جانے کا ایک واسطہ ہی شمار ہوگا۔
جدیدیت کے فکری مسائل
گوکہ جدیدیت کو علمی حوالے سے ایک خاص مقام حاصل ہے خاص کر کہ جب اسے صدر وفاق مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم جیسی بڑی شخصیت تجویز فرمائیں خود مفتی صاحب دامت برکاتہم کے الفاظ میں۔
پروفیسر محمد حسن عسکری مرحوم کی کتاب ” جدیدیت “
” زیر نظر کتاب (جدیدت) آج سے تقریباََ گیارہ سال پہلے حسن عسکری صاحب مرحوم نے احقر کی فرمائش پر ترتیب دی تھی ، مرحوم کا موضوع اگرچہ ادب و تنقید تھا لیکن فلسفہ مغرب پر بھی ان کی گہری نگاہ تھی ، اور فرانس کے ایک معروف فلسفی “رینے گینوں” جن کا اسلامی نام (شیخ عبد الواحد یحییٰ) تھا نے مغربی فلسفے پر جو تنقیدیں کیں عسکری صاحب مرحوم نے ناصرف ان کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا تھا بلکہ وہ ان کے بے حد مداح بھی تھے. ”
آگے فرماتے ہیں:
” احقر کو فرانسیسی زبان سے ناواقفیت کے سبب رینے گینوں کی کتب کے مطالعے کا موقع تو نہ مل سکا لیکن عسکری صاحب مرحوم جب بھی ان کی باتیں سناتے تو ان سے بڑی سلیم ، متصلب ، اور بے آمیز دینی فکر جھلکتی نظر آتی تھی “
یہاں تک کی گفتگو سے چند نکات انتہائی واضح ہو جاتے ہیں۔پروفیسر حسن عسکری مرحوم نے جدیدت رینے گینوں کے افکار سے متاثر ہو کر لکھی۔مفتی تقی عثمانی صاحب کا رینے گینوں کی فکر کا براہ راست مطالعہ نہیں تھا۔ رینے گینوں کی فکر کے حوالے سے حضرت کی رائے عسکری صاحب کے تاثرات تک محدود تھی۔ اب یہاں پر کچھ امور کی وضاحت انتہائی ضروری ہے، اول تو یہ کہ جدیدیت نوے کی دہائی میں لکھی گئی اور آج کہ جب 2022 میں اسے تجویز کیا جا رہا ہے تو حضرت والا کی رینے گینوں کی بابت رائے ابھی تک حسن عسکری صاحب کے تاثرات تک ہی محدود ہے۔
رینے گینوں کون ؟
شیخ عبد الوحد یحیٰی المعروف René Guénon رینے گینوں ( 1951-1886) ممتار و معروف فرانسیسی مسلم دانشور اور ماہر مابعدالطبیعیات تھے۔ آپ کو آنند کمار سوامی اور شون فریژوف کے ہمراہ مکتبۂ روایت پسندی (Traditionalist School) کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ روحانیات، علامات (Symbolism)، کونیات (Cosmology)، تصوف اور مشرقی ما بعد الطبیعیات پر آپ نے دنیا کو نئی فکر سے روشناس کروایا۔ رینے گینوں کے حوالے سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ وحدیت ادیان کے انتہائی قریب چلے گئے تھے اور مغرب پر ان کی تنقید اسی مخصوص دائرے میں دکھائی دیتی ہے ان کی فکر کی ایک جھلک ہم اس حوالے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
رینے گینوں کا تصورِ ’التوحیدُ واحدُُ‘
’’مغرب میں اس سوال (کہ روایت کیا ہے؟)کا جواب صرف ایک شخص نے دیا ہے اور مغرب اس شخص کی بات سننے سے انکاری ہے۔میرا مطلب رُنیے گینوں سے ہے۔وہ (رینے گینوں) کہتے ہیں کہ روایتی ادب اور روایتی فنون صرف روایتی معاشرے میں پیدا ہو سکتے ہیں ۔اور روایتی معاشرہ وہ ہے جو ما بعد الطبیعیات پرقائم ہو۔مابعد الطبیعیات چند نظریوں کا نام نہیں۔التوحیدُ واحدُُ۔مابعدالطبیعیات صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، یہی اصل اور بنیادی روایت ہے ۔اس کا تعلق کسی نسل یا ملک سے نہیں ۔
البتہ اس کے اظہار کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔اور ہندو روایت یا چینی روایت یا اسلامی روایت میں فرق انہی طریقوں کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے۔ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب میں خشکی ہے اور ہندو تہذیب میں حسیات کی رنگا رنگی ہے۔لیکن اپنشد میں لکھا ہے کہ انسانی وجود کے مرکز میں نہ تو سورج کی روشنی ہے نہ چاند کی نہ ستاروں کی،بلکہ ہر چیز پُرش کے نور سے منور ہے۔چنانچہ بنیادی روایت ہر جگہ وہی ہے،صرف شکلوں کا فرق ہے.‘‘
حوالہ:مضمون ’روایت کیا ہے؟‘ ’’وقت کی راگنی ص ۱۰۸
اس عنوان پر جلیل عالی صاحب نے انتہائی شاندار گفتگو فرمائی ہے۔ رینے گینوں کی فکر کا مطالعہ کرنے کے بعد جدیدیت کے حوالے سے بھی متعدد سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جدیدیت میں کیا کمی ہے ؟
جدیدیت یا ماڈرن ازم ایک خاص عنوان ہے اور اس عنوان کے دائرے میں مغرب کے مذہب سے فکری انحراف کی اجمالی تاریخ کو تو ضرور سامنے رکھا گیا ہے لیکن مشرق میں استشراق کے راستے سے آنے والی تجدد پسندی کی بابت اس کتاب میں گفتگو سے گریز کیا گیا ہے۔سرسید سے پرویز تک اور مشرقی سے غامدی تک یہاں تک کہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ سے ڈاکٹر فضل الرحمان ملک تک ہمارے یہاں مذہب کی تشکیک نو کے حوالے سے جو کچھ بھی گفتگو ہوئی ہے وہ اسلامی کی روایتی کلامی فکر اور فلسفے سے کس حد تک مختلف ہے اور کس انداز میں تجدد پسندی کی اس لہر نے انکار روایت ، انکار حدیث اور مسلم فکر و فلسفے کے انکار کا راستہ کھولا ہے.
اس کتاب میں ان عنوانات کو سرے سے نہیں چھیڑا گیا یعنی ہمیں مغربی جدیدیت کی بابت تو کچھ نہ کچھ علم ضرور ملتا ہے لیکن مشرق میں اس کے کیا کچھ اثرات ہوئے اس حوالے سے یہ کتاب خاموش دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب جدید الحاد و دہریت کے حوالے سے اس کتاب میں کوئی خاص مواد موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان عنوانات پر یہ بہتر ذہن سازی کی صلاحیت رکھتی ہے۔
جدیدیت کو کیسے مفید بنایا جا سکتا ہے ؟
یہ بات تو واضح ہے کہ اس کتاب کو پڑھانے کیلیے ایسے رجال کار کی ضرورت ہے کہ جو فلسفہ مغرب سے بخوبی واقفیت رکھتے ہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کلامی روایت اور فکر و فلسفے کے بھی ماہر ہوں۔دوسری جانب یا تو اس کتاب کی تسہیل کی جائے یا پھر جدیدیت کو جدید انداز میں لکھا جائے تاکہ طالب علموں خاص کر مدرسے کے طالب علموں کیلیے یہ کتاب کسی درجے میں مفید ثابت ہو وگرنہ اس کتاب کا تجویز کیا جانا صرف ایک علامتی یا رسمی عمل بن کر رہ جائے گا۔
جدیدیت کے ساتھ کون سی کتب شامل کی جا سکتی ہیں. مغربی فکر و فلسفے کے حوالے سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں ساتھ ہی ساتھ اس کے اثرات کے حوالے سے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے گو کہ یہ کام ایک مستقل کمیٹی کا ہے کہ جو بیٹھ کر اس حوالے سے تخصص کا نصاب تشکیل دے ، جہاں تک میری رائے ہے اس عنوان پر چند ایک کتب انتہائی مفید ہیں۔
اول : انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر
ابو الحسن علی ندویؒ کی اس کتاب کو میں ہمیشہ سر فہرست اسلئے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اس حوالے سے مکمل اعتماد پیدا ہو سکے کہ ہم ہی اس تہذیب کے بانی ہیں کہ جو انسانیت کیلیے خیر لیکر آئی تھی۔
دوم : لا مذہبی دور کا تاریخی پس منظر
مولانا تقی الدین امینی مرحوم کی یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے آج بھی انتہائی مفید شمار کی جا سکتی ہے اس کتاب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخر مذہبی معاشرے لامذہبیت کی طرف کیسے چلے جاتے ہیں۔
سوم : اسلام اور عقلیات
یہ مولانا اشرف علی تھانویؒ کے شاہکار رسالے الانتباہات المفیدۃ عن الاشتباہات الجدیدۃ کی شرح ہے جسے مولانا مصطفیٰ خان بجنوری ؒ نے لکھا ہے جدید عقلی اعتراضات و اشکالات کی بابت اس کتاب میں شاندار اصول بیان کیے گئے ہیں۔
چہارم : سیکولرزم
ڈاکٹر سفر الحوالی کی یہ کتاب مغربی فلسفہ اور جدید مغرب کی سیاسی فکر کے حوالے سے ایک شاہکار ہے اس کتاب میں جدید مغرب کی تاریخ کا ایک مفصل بیان بھی سامنے آ جاتا ہے۔
پنجم : الدین القیم
سید مناظر احسن گیلانیؒ کی یہ کتاب جدید مادیت پرستانہ نظریات کے حوالے سے سد سکندری شمار کی جا سکتی ہے اس کا مطالعہ فلسفہ و تصوف کے طالب علموں کیلیے انتہائی ضروری ہے۔
ششم : دور حاضر کے تجدد پسندوں کے افکار
مولانا یوسف لدھیانوی شہیدؒ کے یہ مضامین انتہائی اہمیت کے حامل ہیں گرچہ اس کتاب میں کچھ مخلصین کی بابت بھی شدید تنقید آگئی ہے جیسے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم یا مولانا علوی مالکی مرحوم یا مولانا اللہ یار خان صاحب مرحوم لیکن کسی بھی جگہ تنقید میں اعتدال سے تجاوز نہیں کیا گیا۔
ہفتم : جدیدیت
پروفیسر حسن عسکری مرحوم کا یہ رسالہ گار اوپر نقل کی گئی کتب کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اسکی بھرپور افادیت سامنے آ سکتی ہے۔میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کے نوجوان علماء کو اگر یہ کتب سال بھر کے تخصص میں درسی انداز میں پڑھا دی جاویں تو انتہائی نفع ہوگا۔


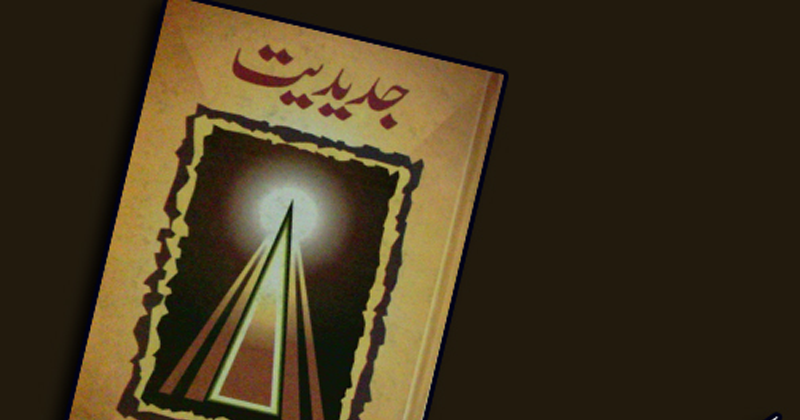



تبصرہ لکھیے